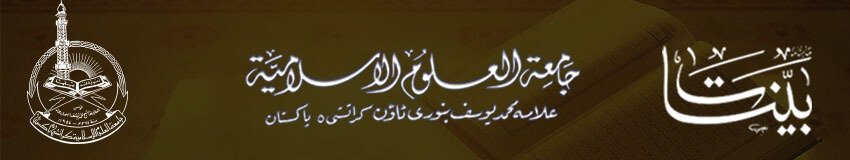
5-’’وَلَا تَجْہَرْ بِصَلَاتِکَ وَلَا تُخَافِتْ بِہَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذٰلِکَ سَبِيْلًا‘‘ (الاسراء: ۱۱۰)
ترجمہ: ’’اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے چپکے ہی پڑھیے اور دونوں کے درمیان ایک طریقہ اختیار کر لیجیے۔‘‘
اس آیت کے ظاہر ی معنی یہ معلوم ہوتے ہیں کہ بالکل پست آواز سے نماز میں قراءت سے منع فرمایا گیا ہے، اسی لیے آج کل بعض نام نہاد اسکالرز کا کہنا ہے کہ اُمت ظہر اور عصر کی نماز قرآن کی تعلیم کے خلاف پڑھ رہی ہے، اب ان صاحب نے آیت کے سیاق وسباق میں غور کرنے کی بجائے چودہ سو سال کی پوری اُمت کے عمل کو غلط قرار دے دیا، کس قدر ناواقفیت اور جہالت پر مبنی دلیری کی بات ہے؟ حقیقت میں اس آیت کے مختلف شانِ نزول بتائے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، نماز کے دوران جب بلند آواز سے قراءت کی جاتی تو مشرکین شور مچا کر اس میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے، اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل آہستہ آواز سے پڑھنا شروع کردیا تو اس پر یہ آیت اُتری کہ اعتدال کے ساتھ قراءت کرو۔ (تفسیر عثمانی) بعض حضرات نے یہ تاویل کی کہ تمام نماز وں میں صرف جہر اور صرف پست آواز سے پڑھنے سے منع فرمایا گیا، بلکہ ظہروعصر میں سرّاً یعنی پست آواز سے پڑھنے اوربقیہ تین نمازوں میں جہراً یعنی بلند آواز سے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بعض حضرات نے کہا: یہ آیت دوسری آیت مبارکہ ’’ادْعُوْا رَبَّکُمْ تَضَرُّعًا وَّخُفْيَۃً إِنَّہٗ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ‘‘ (الاعراف: ۵۵) کی وجہ سے منسوخ ہو چکی ہے۔
6-’’يٰبَنِيْٓ اِسْرَآئِيْلَ اذْکُرُوْا نِعْمَتِيَ الَّتِيْ اَنْعَمْتُ عَلَيْکُمْ وَاَنِّيْ فَضَّلْتُکُمْ عَلَی الْعٰلَمِيْنَ‘‘ (البقرۃ: ۴۷)
ترجمہ: ’’اے بنی اسرائیل! میری اس نعمت کو یاد کرو جومیں نے تم پر کی اور بے شک میں نے تمہیں عالم کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔‘‘
اس آیت سے بعض نام نہاد اسکالرز استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہود مسلمانوں سے افضل ہیں، کیونکہ عالم کے لوگوں میں اہلِ اسلام بھی داخل ہیں، اسی لیے بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہود ونصاریٰ اپنی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزاریں تو یہ بھی نجات کے مستحق ہو ں گے۔ جبکہ یہ استدلال بالکل درست نہیں، کیونکہ اس میں عالمین سے مراد صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے لوگ مراد ہیں، مستقبل کے لوگ اور اُمتیں اس میں شامل نہیں، تمام مفسرین نے اس آیتِ مبارکہ کا یہی مطلب بیان کیا ہے، چنانچہ امام عبدالرحمٰن بن ابوحاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین نے اس کی تصریح کی ہے:
7- ’’عن عائشۃؓ، قالت: قال رسول اللہ - صلی اللہ عليہ وسلم-:’’توضؤوا مما مست النار۔‘‘
ترجمہ: ’’حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا : آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرو۔‘‘
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ پر پکی ہوئی کوئی بھی چیز کھانے سے وضو کرنا واجب ہے، حالانکہ اُمت نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اس صورت میں وضو واجب نہیں ہوتا اور اس پر تمام وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جن میں آپ علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھایا اور پھر وضو نہیں کیا، اسی لیے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لہٰذا اگرکوئی شخص اس حدیث کی بنا پر یہ کہے کہ ایسی صورت میں وضو کرنا واجب ہے تو اُس کا یہ نظریہ درست نہیں ہو گا۔
8-’’عن عباد بن تميم المازني، عن أبيہ أنہٗ قال: ’’ رأيت رسولَ اللہ صلی اللہ عليہ وسلم يتوضأ ويمسح بالماء علی رجليہ۔‘‘
ترجمہ: ’’حضرت عباد اپنے والد تمیم مازنیؓ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور پانی کے ذریعہ اپنے دونوں پاؤں پر مسح کیا۔‘‘
اس حدیث سے پاؤں پر مسح کا جواز معلوم ہوتا ہے، حالانکہ اہل السنہ والجماعہ یعنی جمہور اُمت کا موقف یہ ہے کہ پاؤں پر مسح کرنا جائز نہیں، ایسی صورت میں وضو نہیں ہو گا، یہ حدیث منسوخ ہو چکی ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص اس حدیث کی بنا پر کہے کہ پاؤں پر مسح جائز ہے تو یہ غلط نظریہ ہوگا، جیسا کہ بعض اہلِ عرب اس طرح کی احادیث کی بنا پر پاؤں پر مسح کے جواز کے قائل ہیں۔
9-’’عن جعفر بن عمرو بن أميۃ، عن أبيہ، قال: ’’رأيت النبي صلی اللہ عليہ وسلم يمسح علی عمامتہٖ وخفيہ۔‘‘
ترجمہ: ’’حضرت جعفر بن عمرو بن امیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسو ل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے (وضو کے دوران) اپنے عمامہ اور موزوں پر مسح کیا۔‘‘
اس حدیث سے عمامہ پر مسح کا جواز معلوم ہوتا ہے، حالانکہ جمہور علمائے کرام کے نزدیک عمامہ پر مسح کرنا جائز نہیں، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر’’ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِکُمْ‘‘ (المائدۃ: ۶) کے الفاظ وارد ہوئے ہیں، جو کہ سر پر مسح کے بارے میں صریح ہیں، لہٰذا اس حدیث سے یہ استدلال کرنا پگڑی اور عمامہ پر مسح جائز ہے، درست نہیں۔
10-’’عن أبي ہريرۃؓ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم: ’’من غسل ميتا فليغتسل، ومن حملہٗ فليتوضأ۔‘‘
ترجمہ: ’’حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے اور جو میت کی چارپائی کو اُٹھائے، اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔‘‘
اس حدیث میں جنازہ کی چارپائی اُٹھانے پر وضو کرنے کا حکم دیا گیا، جبکہ ایسی صورت میں وضو کا وجوب کسی اور آیت یا حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا اور اس پر عمل نہیں کیا گیا، کیونکہ دیگر تمام نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے ٹوٹنے کی علت نجاست کا خروج ہے اور وہ علت یہاں نہیں پائی گئی۔
11- ’’عن أبي ہريرۃؓ قال: قال رسول اللہ - صلی اللہ عليہ وسلم -: ’’لا وضوءَ إلا من صوت أو ريح۔‘‘
ترجمہ: ’’حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس وقت تک وضو واجب نہیں جب تک ہوا کے نکلنے کی آواز یا بُو نہ محسوس کر لی جائے۔‘‘
اس حدیث کے ظاہر پر بھی عمل نہیں کیا گیا، کیونکہ اگر کسی شخص کو ہوا کے خروج کا یقین ہو جائے، مگر زکام وغیرہ کی وجہ سے اس کو بو محسوس نہ ہو اور بہرہ ہونے کی وجہ سے اس کو آواز بھی سنائی نہ دے تو بھی اس شخص کا بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا، لہٰذا اگر کوئی شخص اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے آواز اوربُو محسوس نہ ہونے کی صورت میں وضو کے عدمِ وجوب کا موقف اختیار کرے تو یہ واضح غلطی اور خطا ہوگی۔
12- ’’قال رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم: ’’إن ہٰذا القرآن أنزل علی سبعۃ أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منہ۔‘‘
ترجمہ:رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک یہ قرآن سات حروف پر نازل ہوا ہے، پس اس میں سے جتنا آسانی سے ہو پڑھو۔‘‘
اس حدیثِ پاک میں ’’سبعۃ أحرف‘‘ سے سات حروف مراد نہیں، بلکہ قرآن کو سات طریقوں سے پڑھنا مراد ہے، جس کی تفسیر میں محدثین اور قراء کرام کا اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ احادیثِ مبارکہ میں غریب احادیث (ایسی احادیث جن کا معنی لغوی اعتبار سے مشکل ہونےیا ان کے الفاظ میں کئی معانی کا احتمال ہونے کی وجہ سے صحیح مراد تک پہنچنا مشکل ہو) کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے، ان احادیث کے درست معنی کی تعیین علمائے کرام رحمۃ اللہ علیہم کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے محدثین کرام نے ایسی احادیث کے معنی کی تعیین کے لیے غرائب احادیث کے نام سے مختلف کتابیں لکھی ہیں۔
پیچھے ذکر کی گئی وجوہ سے معلوم ہوا کہ اُمت جب کسی قرآن یا حدیث کے ظاہری معنی پر عمل پیرا نہیں ہوتی تو اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ ہوتی ہے، لہٰذا کسی بھی آیت اور حدیث کا وہی مفہوم اور مطلب لینا ہو گا جس کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ، امت کے جمہور مفسرین، محدثین اور فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہم نے معتبر قرار دیا ہے، اس مفہوم سے ہٹ کر کسی بھی آیت یا حدیث کی تشریح ناقابلِ قبول ہے، لہٰذا ایسی تشریح اگر ضروریاتِ دین یا شریعت کے کسی قطعی امر کے خلاف ہو تو ایسی تشریح پیش کرنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گا، اس کی تاویلِ باطل کو کالعدم شمار کیا جائے گا اور اس کی یہ تاویل اس کے گمراہ ہونے سے مانع نہیں ہوگی، لہٰذا عام آدمی کے لیے قرآن وسنت کی عبارات کے صحیح معانی اور درست مطالب تک پہنچنے کے لیے درج ذیل تین اصولوں میں سے کسی ایک اصول کو لینا ہوگا:
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہِ راست دین سیکھا اور اُن کےواسطہ سےہی دین امت تک پہنچا، اس لیے قرآن وسنت کی درست تفسیر اورتشریح کے سلسلہ میں ان کی تشریحات کو معیار قرا ر دیا جائے، چنانچہ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ میری اُمت کے تہتر فرقے ہوں گے، سب جہنم میں جائیں گے ، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، عرض کیا گیا: وہ کون سا فرقہ ہو گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے راستے پر چلنے والا ہو گا، دیکھیے حدیث:
’’عن عبد اللہ بن عمرو، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم: ’’ليأتين علی أمتي ما أتی علی بني إسرائيل ............وإن بني إسرائيل تفرقت علی ثنتين وسبعين ملۃ، وتفترق أمتي علی ثلاث وسبعين ملۃ، کلہم في النار إلا ملۃ واحدۃ‘‘، قالوا: ومن ہي يا رسول اللہ؟ قال: ’’ما أنا عليہ وأصحابي۔‘‘
ترجمہ: ’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک میری امت پر وہی زمانہ آئے گا جو بنی اسرائیل پر آیا تھا۔۔۔۔۔ بنی اسرائیل کے بہتر فرقے بنے تھے ، میری اُمت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو گی، ایک فرقہ کے علاوہ باقی تمام فرقے جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وہ کون سا فرقہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو میرے اور میرے اصحابؓ کے راستے پر چلے گا۔‘‘
دوسرا اُصول یہ ہے کہ قرآن وسنت کی تشریح میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے کے جمہور علمائے کرام کی تشریح کو معيار قرار دیاجائے، کیوں کہ ان کے خیر پر ہونے کی گواہی بھی حدیث میں آئی ہے، دیکھیے حدیث:
’’عن عبد اللہ، قال: قال رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم: ’’خير أمتي القرن الذين يلوني، ثم الذين يلونہم ثم الذين يلونہم۔‘‘
ترجمہ: ’’حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری امت میں سے سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں اور پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہوئے ہیں۔‘‘
لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تبع تابعین تک کے زمانے کے جمہور علمائے کرام نے قرآن وسنت کی کسی آیت یا حدیث کا جو مطلب بیان کیا ہو وہی برحق ہو گا اور جو اس کے خلاف ہو وہ باطل شمارہو گا۔
تیسرا اصول یہ ہے کہ پوری امت کی اکثریت کا قول لیا جائے کہ امت کی اکثریت نے کس آیت کا کیا مطلب لیا ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ کی حدیث میں ہے کہ میری پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، بعض ضعیف روایات میں یہ بھی منقول ہے کہ جب تم میری امت کے درمیان اختلاف پاؤ تو امت کی اکثریت کا اتباع کرو، دیکھیے حدیث:
’’حدثني أبو خلف الأعمی، قال: سمعت أنس بن مالک، يقول: سمعت رسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم، يقول: ’’إن أمتي لا تجتمع علی ضلالۃ، فإذا رأيتم اختلافا فعليکم بالسواد الأعظم۔‘‘
ترجمہ: ’’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک میری پوری اُمت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، پس جب تم میری اُمت میں کسی قسم کا اختلاف پاؤ تو تم امت کی اکثریت کے اتباع کو لازم پکڑو۔‘‘
اس کی تائید ایک دوسری روایت سے بھی ہوتی ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت جماعت کے ساتھ ہے اور یہاں جماعت سے مراد امت کی اکثریت ہے۔ نیز قرآن کریم کی درج ذیل آیت مبارکہ سے بھی یہ مفہوم ثابت ہوتا ہے:
’’وَمَنْ يُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَہُ الْہُدَی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيْلِ الْمُؤْمِنِيْنَ نُوَلِّہٖ مَا تَوَلّٰی وَنُصْلِہٖ جَہَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيْرًا‘‘ (النساء: ۱۱۵)
ترجمہ: ’’اور جو شخص اپنے سامنے ہدایت واضح ہوجانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور مومنوں کے راستے کے سواکسی اور راستے کی پیروی کرے، اس کو ہم اسی راہ کے حوالے کر دیں گے جو اس نے خود اپنائی ہے اور اسے دوزخ میں جھونکیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانا ہے۔‘‘ (آسان ترجمۂ قرآن)
اس آیتِ مبارکہ میں واضح طور پر مؤمنین کے راستے کے علاوہ دوسرے راستے کے گمراہی پر ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس پر دوزخ کی وعید سنائی گئی ہے، نیز یہاں مومنین سے اُمت کی اکثریت مراد ہے، جیسا کہ پیچھے ذکرکردہ احادیث سے معلوم ہوا۔
خلاصہ یہ کہ آج کے دور میں اگر کوئی شخص عقائد یا دینی مسائل واحکام کے حوالے سے اپنی کوئی رائے پیش کرتا ہے تو ان چار اصولوں پر پرکھنا ہوگا، اگر ان کے موافق ہے تو اس کا موقف قبول ہوگا، ورنہ رد کر دیا جائے گا، لہٰذا آغا خانی حضرات کا صوم کا معنی ’’خاموش رہنا‘‘ کرنا، اسماعیلی حضرات کا صلاۃ سے ’’دعا‘‘ مراد لینا اور قادیانیوں کا ختمِ نبوت سے صرف تشریعی نبوت کو ختم ماننا اور غیر تشریعی نبوت کو جاری سمجھنا بالکل غلط اور باطل ہے، اسی طرح کسی شخص کا ختمِ نبوت یا نزولِ مسیح علیہ السلام سے متعلقہ آیات میں تاویل کر کے کسی قسم کی نبوت کو جاری ماننا یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و نزول کا انکار کرنا بلاشبہ کفر ہے، چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ’’شفاء العلیل‘‘ میں فرماتے ہیں:
’’والتأويل الباطل يتضمن تعطيل ما جاء بہ الرسول والکذب علی المتکلم أنہٗ أراد ذلک المعنی، فتتضمن إبطال الحق وتحقيق الباطل ونسبۃ المتکلم إلی ما لا يليق بہ من التلبيس والألغاز مع القول عليہ بلا علم أنہ أراد ہذا المعنی، فالمتأول عليہ أن يبين صلاحيۃ اللفظ للمعنی الذي ذکرہٗ أولا، واستعمال المتکلم لہ في ذلک المعنی في أکثر المواضع حتی إذا استعملہ فيما يحتمل غيرہ حمل علی ما عہد منہ استعمالہ فيہ، وعليہ أن يقيم دليلا سالما عن المعارض علی الموجب لصرف اللفظ عن ظاہرہٖ وحقيقتہٖ إلی مجازہٖ واستعارتہٖ وإلا کان ذٰلک مجرد دعوی منہ، فلا تقبل. ‘‘
البتہ قرآن وحدیث کی ایسی تشریح اور تاویل جو امت کے اجماعی موقف کے خلاف نہ ہو اور اس کی وجہ سے کسی قطعی حکم کا انکار لازم نہ آتا ہو تو وہ جائز ہے، چنانچہ مفسرین کی تفسیری آراء اور محدثین کرام کی تشریحات اسی پر محمول ہیں۔