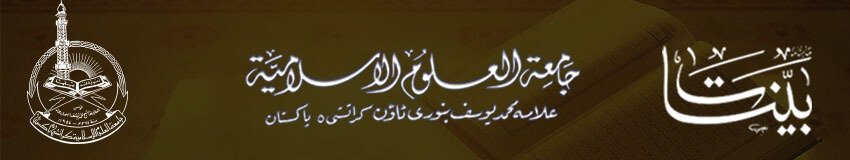
محدثِ جلیل حضرت مولانا مفتی سعیداحمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ مؤرخہ ۷ ا؍ذو الحجہ۱۴۲۱ھ کوقدیم دینی وملی تنظیم امارتِ شرعیہ پھلواری شریف پٹنہ تشریف لائے۔ وہاں آپ نے سابق صدر مسلم پرسنل لا بورڈ حضرت مولانا قاضی مجاہدالاسلام قاسمی نوراللہ مرقدہٗ کی عیادت فرمائی اور ذمہ دارانِ امارتِ شرعیہ کی خواہش پر آپ نے بعد نماز عشاء المعہدالعالی ہال میں افتاء وقضاء کے طلبہ اور دارالعلوم الاسلامیہ کے طلبہ سے انتہائی بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ اجلاس کی صدارت دارالعلوم دیو بند کے معزز رکن شوریٰ امیر شریعت حضرت مولانا سید نظام الدین جنرل سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کی اور نظامت کے فرائض بندہ خالد نیموی قاسمی نے انجام دیے۔ اس جامع دینی خطاب کو بندہ نے محفوظ کر لیا تھا۔ ترتیبِ جدید کے بعد افادئہ عام کے لیے شائع کیا جارہا ہے۔ (مرتّب)
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد النبي الأمین وعلی آلہٖ وصحبہٖ أجمعین!
انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی اشرفیت و افضلیت کی دلیل یہ ہے کہ اس نے اس بارِ امانت کو اُٹھالیا ہے، جس کا تذکرہ اس آیتِ کریمہ میں ہے :
’’إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَیْنَ اَنْ یَّحْمِلْنَہَا وَاَشْفَقْنَ مِنْہَا وَحَمَلَہَا الْإِنْسٰنُ إِنَّہٗ کَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا‘‘ (الاحزاب:۷۲)
یعنی ’’بے شک ہم نے اپنی امانت آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کی، تو انھوں نے اسے اُٹھانے سے انکار کردیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اُسے اُٹھالیا، وہ بے شک بڑا ہی ظالم، نادان تھا۔‘‘ (الاحزاب :۷۲)
اس آیتِ کریمہ کی تشریح وتفسیر کی آپ جیسے اہلِ علم کے سامنے چنداں حاجت نہیں۔ اس کے چند ٹکڑے اشارتاً ذکر کرتا ہوں، جس سے ساری آیت خود بخود سمجھ میں آجائے گی۔
مذکورہ آیت میں ایک محوری لفظ ہے: ’’امانت‘‘، ’’إِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَۃَ‘‘ میں امانت کے معنی تقریباً وہی ہیں جو اردو میں ہیں، اردو میں امانت کہتے ہیں حفاظت کی ذمہ داری کو، کسی بھی چیز کی حفاظت کی ذمہ داری کو امانت کہتے ہیں۔ آپ حضرات انگریزی پڑھتے ہیں؛ اس لیے انگریزی لفظ استعمال کروں کہ رسپونسی بلیٹی (Responsibility) امانت کی انگریزی تفسیر ہے۔
مشہور حدیث ہے: ’’ لا إیمان لمن لا أمانۃ لہ‘‘، ’’جس شخص میں امانت نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں ہے۔‘‘ اس حدیث شریف میں امانت کا لفظ اسی معنی میں آیا ہے۔ ایک شخص ہے، ہم نے اس سے ایک بات کہی، اس سے یہ کہا کہ بھائی صاحب! یہ بات کسی سے مت کہنا۔ اب یہ بات اس کے پاس امانت ہے، یعنی اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس پر ہے، اب اگر وہ اس بات کو آگے بڑھاتا ہے، کسی دوسرے سے کہتا ہے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ ایک آدمی کے پاس آپ نے پیسہ رکھا، زر رکھا، سونارکھا، چاندی رکھی، یا کوئی اور قیمتی چیز رکھی کہ میرا گھر محفوظ نہیں ہے، اس لیے اسے آپ رکھ لیں، میں سفر پرجارہا ہوں؛ اسے آپ رکھ لیں، یہ امانت ہے، یعنی اس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری اس شخص پر ہے۔ یہ میں نے چند چیزیں ذکر کیں، تاکہ آپ لفظِ امانت کا مفہوم سمجھ سکیں کہ امانت کیا چیز ہے؟
کوئی چیز ہوتی ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری کا نام امانت ہے، وہ چیز کیا ہے؟ وہ آپ حضرات سمجھتے ہیں۔
اللہ جل شانہ نے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کرنبی پاک k تک انبیاء کرام کے ذریعے آسمانوں سے جو ہدایت بھیجی، آسمانوں سے جو دین بھیجا ہے، یہی وہ عظیم شئے ہے، جس کی حفاظت کرنے کا نام امانت ہے، ظاہر ہے کہ یہ کوئی محسوس چیز تو ہے نہیں کہ مثلاً یہ گھڑی رکھی ہے، اسے بکسے میں بند کر دیا، محفوظ جگہ رکھ دیا یا مثلاً چابی ہے تو اُسے جیب میں رکھ لیا، تاکہ گھڑی اور چابی کی حفاظت ہو جائے، یہ تو اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جو دین بھیجا ہے وہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کی شکل یہ نہیں کہ اُسے تالے میں بند کر کے جیب میں اس کی چابی رکھ لی جائے، بلکہ اس کی شکل کوئی اور ہے۔ یہ ایک لفظ، لفظ ِامانت کی شرح ہے۔
دوسرا لفظ ہے: ’’عَرَضْنَا‘‘ یعنی پیش کیا ہم نے۔ پیش کرنا کیا ہے؟ کبھی مجلس میں تھالی لے کر کوئی ملازم آتا ہے، اس تھالی میں سونف ہے، چھالیہ ہے، لونگ، الائچی وغیرہ ہے اور سب کے سامنے گھماتا گھماتا لے چلتا ہے، جس کی خواہش ہے، اسے لے گا اور جسے خواہش نہیں وہ چپ چاپ بیٹھا ر ہے گا اور تھالی آگے بڑھ جائے گی۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی قدس سرہٗ نے حجۃ اللہ البالغۃ میں حضرت قاضی بیضاویؒ اور امام غزالی ؒ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ پیش کرنے کا مطلب ’’مخلوقات کی استعدادوں کے ساتھ موازنہ کرنا ہے‘‘ کہ اس امانت کو اُٹھانے کی استعداد و صلاحیت کس میں ہے؟ یہ جو موازنہ کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ پیش کرنا ہے۔ ایسا کوئی محسوس نہیں ہے کہ اس امانت کو رکھ کر سارے مخلوق کے سامنے لے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یہاں مفہوم معنوی طور پر پیش کرنا ہے اور وہ ہے استعدادوں کے ساتھ موازنہ کرنا۔
تیسرا لفظ ہے: ’’فَأَبَیْنَ أَنْ یَّحْمِلْنَہَا‘‘ آسمانوں اور زمین نے اور پہاڑوں نے انکار کر دیا اس امانت کو اُٹھانے سے۔ مراد یہ تین ہی مخلوقات نہیں ہیں، یہ تو انسانوں کے سامنے جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ ’’عَلَی السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ‘‘ فرمایا، آپ غور کیجئے! آپ اوپر نگاہ اُٹھائیے! کہ آسمان سے بڑی طاقتور دیرپا کوئی مخلوق نہیں ہے، پیروں کی طرف دیکھیے! تو زمین سے زیادہ مضبوط اور دیر پا کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے اور بیچ میں آسمان کے نیچے فلک بوس پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں، معلوم نہیں کب سے کھڑے ہیں، جب سے زمین پیدا ہوئی کھڑے ہیں اور اپنی جگہ سے ٹَس سے مس نہیں ہورہے ہیں؛ لہٰذا ان تین مخلوقات کی استعدادوں کے ساتھ موازنہ کرنے کا مطلب ہے تمام مخلوقات کے ساتھ موازنہ کرنا۔ کون سی مخلوقات مراد ہیں؟ تو سمجھیے کہ یہاں نورانی مخلوق یعنی وہ جو آسمانوں کے فرشتے ہیں وہ زیرِ بحث نہیں، اس سے مراد زمینی مخلوقات ہیں: چرند ہوں، پرند ہوں، کیڑے ہوں، مکوڑے ہوں، خاک کے ذرے ہوں، شجر ہوں، حجر ہوں۔ تمام مخلوقات کے سامنے یہ امانت پیش کی گئی، یعنی ان کی صلاحیتوں کے ساتھ موازنہ کیا گیا؛ چنانچہ دنیا کی کسی بھی مخلوق میں اس امانت کو اُٹھانے کی استعداد نہیں پائی گئی، یہ جو استعداد نہیں پائی گئی، یہی انکار کرنے کا مطلب ہے۔
یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قاضی بیضاویؒ اور امام غزالی ؒ کے حوالے سے لکھی ہے کہ اس آیت میں ’’اِبَاء‘‘ کا مطلب اباء طبعی ہے، یعنی ان میں سے کسی میں یہ استعداد نہیں پائی گئی۔ اباء اختیاری اور ابا ء قولی مراد نہیں؛ اس لیے کہ اباء قولی اگر کوئی مخلوق کرتی ہے تو وہ انسان کرتا ہے۔ انسان کے علاوہ کوئی بھی مخلوق اباء قولی نہیں کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ کے لیے سجدہ ریز ہیں تمام چیزیں :
’’اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللہَ یَسْجُدُ لَہٗ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِی الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَاۗبُّ وَکَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ۰ۭ وَکَثِیْرٌ حَقَّ عَلَیْہِ الْعَذَابُ۰ۭ وَمَنْ یُّہِنِ اللہُ فَمَا لَہٗ مِنْ مُّکْرِمٍ۰ۭ اِنَّ اللہَ یَفْعَلُ مَا یَشَاۗءُ‘‘ (الحج : ۱۸)
یعنی ’’کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اورجو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اورستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ (بھی)ہیں جن پر عذاب مقرر ہوچکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کرے تواسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔‘‘
یہاں نجوم، شجر اور جبال کے ساتھ ’’وَکَثِیْرٌ مِّنَ النَّاسِ‘‘ ہے، اس لیے کہ اباء قولی صرف انسان میں پایا جاتا ہے، دوسری کسی مخلوق میں یہ صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ انسان کے علاوہ خدا کی جو مخلوق آسمان و زمین کے درمیان ہے، وہ ہمہ وقت اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے، لہٰذا وہ مخلوق تو ہمہ وقت اللہ کی تسبیح خواں ہے، اس سے یہ اُمید کرنا، ان سے یہ توقع کرنا کہ وہ انکار کرے، یہ درست نہیں ہوسکتا۔
’’اَبَیْنَ‘‘ کا مطلب ہے: اباء طبعی، یعنی موازنہ کرنے کے عمل سے یہ ثابت ہوا کہ کسی مخلوق میں اس امانت کو اُٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے، اس کی حفاظت کرنے کی استعداد اُن میں نہیں پائی گئی۔
آیتِ کریمہ کا اگلا حصہ ہے: ’’وَاَشْفَقْنَ مِنْہَا‘‘ پہلے یہ سمجھیے! کہ نہ پائے جانے کے بھی کئی درجے ہیں، کسی ایک چیز کے نہ پائے جانے کی استعداد کے بھی درجے ہیں، ایک درجہ ہے صفر اور ایک ہے زیرو صفر، یا پوائنٹ صفر یعنی سوواں حصہ بھی نہیں ہے اور پوائنٹ صفر یعنی ہزارواں حصہ بھی نہیں ہے۔ منطق کی اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں مطلق، یعنی مطلق استعداد اس میں نہیں پائی گئی۔ یہی ’’أَشْفَقْنَ مِنْہَا‘‘ کے معنی ہوئے۔
’’وَحَمَلَہَا الْاِنْسٰنُ‘‘ یعنی اس بارِ امانت کو اُٹھانے کی استعداد انسان میں پائی گئی، یعنی یہ پیش کرنا تو بدوِ کائنات یعنی ابتدائے آفرینش میں ہے، اللہ نے جب کائنات پیدا کی ہے، تو پیش کیا ہے، انسان تو ابھی وجود میں بھی نہیں آیا تھا۔
’’إِنَّہٗ کَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا‘‘: حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے مہتمم سادس ہیں، حجۃاللہ البالغۃ کے درس میں اپنی طرف سے ’’حکمتِ قاسمیہ‘‘ کے وارث کے طور پر اضافات فرمایا کرتے تھے، ایسی باتیں عام طور پر ارشادفرمایا کرتے تھے، جواگرچہ حجۃ اللہ البالغۃ میں نہیں ہوتیں؛ لیکن اس کے مضامین کی ان سے تکمیل ضرور ہوتی تھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ: ’’إِنَّہٗ کَانَ ظَلُوْمًا جَہُوْلًا‘‘ میں انسان کی تعریف کی گئی ہے۔ کس طریقے پر تعریف کی گئی؟ حضرتؒ فرماتے تھے کہ ’’ظالم‘‘ کے مبالغہ کا صیغہ ’’ظلوم‘‘ ہے۔ ’’ظالم‘‘ اُسے کہیں گے جس میں انصاف کرنے کی استعداد ہو اور وہ انصاف نہ کرے؛ اس لیے دیوار کو ظالم نہیں کہیں گے ؛ اس لیے کہ اس میں انصاف کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح ’’جاہل‘‘ اور ’’جہول‘‘ اسے کہا جائے گا، جس کی اصل شان تو یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے اور پھر وہ علم حاصل نہ کرے؛ بلکہ نرا جاہل اور گنوار رہ جائے، تو وہ ’’جاہل‘‘ ہے۔ اس کی ڈگری جب بڑھ جاتی ہے، تو وہ ’’جَہول‘‘ بن جاتا ہے۔ دیوار کو نہ تو جاہل کہہ سکتے نہ جہول، اس لیے کہ اس میں مطلق علم حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تعریف کی ہے، اس کے دو پہلو ہیں: ایک یہ کہ انسان علم اور عدل و انصاف کے پہلو پر چلے گا تو اتنی دور تک پہنچ جائے گا کہ کوئی اس کی خاک کو بھی نہیں پاسکے گا، اتنی دور چلا جائے گا جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ:
عیاں گر دیدہ می گنجد نہاں در سینہ می گنجد
مگر مردِ آفاقی در دو عالم نمی گنجد
اور اگر خدانخواستہ انسان اس کی مقابل راہ اختیار کرے، جہالت کی راہ پر چلے، ظلم کے راستے پر چلے، تو اسے بھی کوئی نہیں پکڑسکتا۔ وہ اتنی دور جائے گا کہ ’’جاہل‘‘ نہیں، ’’جہول‘‘ ہو کر رہ جائے گا، ’’ظالم‘‘ نہیں ’’ظلوم‘‘ بن کر رہ جائے گا۔ ضدّین کی اس میں پوری صلاحیتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پہلو کو ذکر کیا اور اس کا مقابل پہلو مخاطبین کی فہم پر چھوڑ دیا کہ خود ہی سمجھنے کی کوشش کریں۔
قرآن کا ایک خاص اُسلوب ہے کہ وہ بہت سی جگہوں پر آدھا مسئلہ بیان کرتا ہے اور آدھا حکمت کے تحت چھوڑ دیتا ہے۔ عام طور پر اسے مخاطبین کی فہم پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ایسا موقع محل کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:
’’قُلِ اللّٰہُمَّ مٰلِکَ الْمُلْکِ تُؤْتِی الْمُلْکَ مَنْ تَشَاۗءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْکَ مِمَّنْ تَشَاۗءُ۰ۡ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاۗءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاۗءُ۰ۭ بِیَدِکَ الْخَیْرُ۰ۭ اِنَّکَ عَلٰی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ‘‘ (آلِ عمران:۲۱)
ترجمہ: ’’یوں عرض کرو: اے اللہ! ملک کے مالک! تو جسے چاہتاہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور توجسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تمام خیر تیرے ہی قبضۂ قدرت میں ہے، بیشک تو ہر شے پر قدرت رکھنے والاہے۔‘‘ (آل عمران :۲۱)
اس آیت کے اخیر میں فرمایا گیا کہ: تمام ’’خیر‘‘ اللہ کے قبضے میں ہے، سوال یہ ہے کہ ’’شر‘‘ کس کے قبضے میں ہے ؟ اہل السنۃ والجماعۃ کا عقیدہ ہے کہ خیرو شر دونوں اللہ کے قبضہ میں ہیں، تو پھر آدھا مسئلہ بیان کر کے آدھے کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ آدھے کو مخاطب کے فہم پر چھوڑ دیا گیا؛ اس لیے کہ یہ موقع اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کا ہے اور اللہ کی تعریف کے موقع پر دوسری ضد کو بیان کرنا مصلحت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ ’’شرح عقائدِ نسفیہ‘‘ میں آپ نے پڑھا ہے، ’’عذاب القبر حقٌ‘‘یعنی عذابِ قبر برحق ہے؛ لیکن یہ پورا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک حصہ کو چھوڑ دیا گیا ہے، اس لیے کہ قبر میں صرف عذاب ہی نہیں، بلکہ نیک بندوں کو نعمت بھی بہم پہنچائی جاتی ہے۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحبؒ فرماتے تھے کہ: اگر اس آیت میں برائی ہے، توان انسانوں کی برائی ہے، جو حق کی امانت ادا نہیں کرتے، لیکن جو مؤمنین حق کی امانت اداکرتے ہیں، ان کی برائی اس میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ان کی تعریف ہے۔
یہ آیتِ کر یمہ کے چند اجزاء تھے، جو میں نے سمجھائے۔ اب آگے بڑھیے، یہ جو اُٹھانا ہے کہ انسان نے اس بوجھ کو اُٹھالیا، یہ منطقی اصطلاح میں کلّی مشکّک ہے، چوں کہ اُٹھانا معنوی ہے اور اس کے درجے الگ الگ ہیں، جس طرح احمر، ابیض واسود کے بے شمار در جے ہیں، اسی طرح اُٹھانے کے بھی بے شمار درجے ہیں۔
دو حدیثوں کو ذہن میں لائیے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے غصہ اور طیش میں آکراپنی گونگی باندی کو تھپڑ ماردیا۔ جلدہی انھیں اپنے اس عمل پر پچھتاوا ہوا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، صورت حال کو بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو بلواکر پوچھا: ’’أین اللہ؟‘‘ یعنی اللہ کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا کہ وہ آسمان میں ہے، آپ نے پوچھا: ’’من أنا؟‘‘ کہ میں کون ہوں تو وہ جواب میں، ’’انت رسول اللہ‘‘ نہیں کہہ سکتی تھی؛ بلکہ آسمان کی طرف ہاتھ اُٹھایا، پھر آپ کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اس حدیث پرا شکال ہوتا ہے کہ اللہ تومکان سے منزہ ہیں اور اللہ کے رسول اس کے جواب پر فرماتے ہیں: ’’اعْتِقْہا فإنہا مؤمنۃٌ‘‘ تم اسے آزاد کردو، اس لیے کہ وہ مومنہ ہے۔یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں۔
دوسری حدیث یہ ہے کہ ایک جوان آدمی تھا جس نے اپنے اوپر ظلم اور گناہ کررکھا تھا، جب اس کی موت کا وقت آیا، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا کر آدھی راکھ کو خشکی میں اور آدھی کو سمندر میں پھینک دینا، تاکہ میں خدا کے عذاب سے بچ جاؤں؛ اس لیے کہ اگر خدا کا بس چل گیا تو وہ مجھے درد ناک عذاب دے گا، اس لیے کہ میں نے بے تحاشا گناہ کیے ہیں۔ وہ شخص وصیت کر کے مرگیا، وصیت کے مطابق اس کی اولاد نے اس کے ساتھ ایسا ہی کیا؛ لیکن اللہ نے خشکی اور سمندر کو حکم دیا اور اس راکھ کو جمع کر کے اس کو زندہ کردیا، پھر اللہ نے پوچھا کہ میرے بندے تو نے تدبیر کیوں کی تھی؟ اس نے وہی جواب دیا کہ پروردگارِ عالم! میں نے آپ کے خوف سے ایسا کیا کہ اگر آپ کا بس چل گیا تو آپ بڑا دردناک عذاب دیں گے۔‘‘ (مشکوٰۃ: ۲۰۷) اس حدیث کو ذکر کر کے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس شخص کی بخشش ہوگئی ؛ اس لیے کہ وہ مومن تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ: جہاں میری صفت ’’شدید العذاب‘‘ ہے، وہیں میں ’’غفور رحیم‘‘ بھی ہوں، تم اس صفت کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور اللہ نے اس کی بخشش کردی، محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ سے اس قدر ڈرا۔
شاہ صاحبؒ لکھتے ہیں کہ یہ ایمان کیسے ہوا ؟ وہ تواللہ کو قادرِ مطلق نہیں مان رہا ہے؟ وہ تو مان رہا ہے کہ میری راکھ اس طرح بکھیر دی جائے گی تو خدا کا بس اس پر نہیں چلے گا اور وہ میری مٹی کو نہیں جمع کر سکے گا، وہ قادرِ مطلق نہیں مانتا تو بھی وہ مومن کیسے ہوا؟ اس کے بعد حضرت شاہ صاحبؒ نے ایک جملہ جواب کے طور پر لکھا کہ ہر شخص سے مطلوب وہ بات ہے، جو اس کی استعداد میں ہے، ہر شخص کی جتنی استعداد ہے، اتنا ہی اس سے مطلوب ہے۔ آپ حضرات سے ہم پوچھیں کہ: ’’أین اللہ؟‘‘ اور آپ کہیں کہ ’’ھو في السماء‘‘، وہ جواب درست نہیں ہوگا؛ اس لیے کہ آپ کی استعداد اس سے بہتر جواب کی ہے؛ لیکن اس باندی کا جواب قبول کرلیا گیا، اس لیے کہ باندی گونگی تھی، اس کی استعداد اتنی ہی بات کی تھی اور وہ آدمی اتنی ہی استطاعت رکھتا تھا کہ راکھ کے جمع کرنے پر خدا کو قادر نہ مانے، تو اللہ نے جتنی استطاعت دی، اس کے موافق اس کا جواب قبول کرلیا۔
مجھے اس سے یہ سمجھانا ہے کہ انسانوں میں جو امانت اُٹھانے کی استعداد ہے، اس کا کمتر درجہ یہ ہے اور اعلیٰ درجہ وہ ہے جو انبیائے کرامؑ اور ان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیائے کرامؒ اور بڑے بڑے لوگوں کو حاصل ہے، اس مقام کی تشریح مشکل ہے۔ البتہ ایک مشہور جملہ ہے: ’’حسنات الأبرار سیئات المقربین۔‘‘ اس جملے میں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ابرار ایک کام کرتے ہیں تو وہ اُن کے لیے حسنہ ہے؛ لیکن وہی کام اگر مقربین کریں تو وہ حسنہ نہیں، بلکہ ان کے لیے سیئہ ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ : ’’ما عرفناک حقَ معرفتک‘‘ آپ کے پہچاننے کا جو حق ہے ہم اس تک نہیں پہنچے، اس حق تک پہنچیں گے جب اس کا خاص وقت آئے گا اور وہ وقت ہے مرنے کے بعد قبر کی زندگی یعنی عالم برزخ میں۔ یہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی اور پھر میدانِ حشر میں بھی بڑھے گی، پھر جنت کی ابدی زندگی میں بڑھتی چلی جائے گی، حضرت شاہ صاحبؒ نے لکھا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے ایک لمبے عرصہ بعد جو علوم حاصل ہوں گے وہ درجہ تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔جس درجے میں امانت اٹھائی، اسی درجہ میں حق اداکریں!
اس تفصیل کے عرض کرنے کا مقصد یہ جاننا ہے کہ آپ حضرات کس درجہ میں ہیں؟ یہ جو امانت اٹھائی ہے سبھی انسانوں نے اٹھائی ہے، آپ نے بھی اٹھائی ہے، ہم نے بھی اٹھائی ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ ہم نے کس درجہ میں وہ امانت اٹھائی ہے؟ اگر ہم اس درجہ کا حق ادا کریں گے، تو سر خرو ہوں گے۔ اگر اس درجہ کا حق ادا نہیں کریں گے تو ناکام رہیں گے۔ اگر ہم مقربین میں ہیں اور ابرار والے حسنات کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے کافی نہیں، وہ تو آپ کے لیے سیئات بن جائیں گی۔ آپ مقربین میں ہیں تو مقربین والا عمل کرنا ہوگا، اس کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علم کا سب سے نچلا درجہ فرض عین ہے، جس کی تحصیل ہر انسان پر لازم ہے، یہ جو فرضِ عین ہے اس کے بھی درجے ہیں، پھر اس کے اوپر جو درجہ ہے وہ فرضِ کفایہ ہے اور آپ جو کچھ حاصل کر رہے ہیں وہ فرضِ کفایہ کا اونچا درجہ ہے، پہلے جو تعلیمی صورت حال تھی اس کے مقابلہ میں صورت حال بدل گئی ہے اور اب آپ جیسے طلبہ کے لیے بھی نگرانی متعین کرنی پڑتی ہے۔
موتی سمندر کے اوپر نہیں ملتے۔ (اس کے بعد حضرت پالن پوری صاحبؒ نے مولانا عبدالحئی فرنگی محلیؒ کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ!)
حضرت مولانا عبدالحئی صاحب فرنگی محلیؒ ایک روز کمرے میں مطالعہ کررہے تھے، دورانِ مطالعہ پانی طلب کیا، ان کے والد حضرت مولانا عبدالحلیم صاحب تشریف فرما تھے، ان کو فکر ہوئی کہ مطالعہ کے دوران ذہن کسی اور طرف کیسے گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہ پڑھے گا، حکم دیا کہ بجائے پانی کے ارنڈی کاتیل جو وہاں رکھا ہوا تھا دے دیا جائے، مولانا عبدالحئی صاحب نے گلاس منہ میں لگایا، تیل پی گئے اور یہ احساس نہ ہو اکہ تیل ہے یا پانی؟ اس کے بعد پھر مطالعہ میں مشغول ہوگئے، والد کی فکر دور ہوئی اور کہا کہ اُمید ہے کہ پڑھ لے گا، والد صاحب چونکہ بہت بڑے طبیب بھی تھے؛ اس لیے صاحبزادے کودواپلاکر تیل کا اثر زائل کردیا۔
( اس واقعہ سے نتیجہ نکالتے ہوئے فرمایا:)
میرے عزیزو! آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ ایک ماہر غواص بن جائیے، جو اتنی گہرائی میں چلا جائے کہ دنیا و مافیہا سے وہ بے خبر ہوجائے، اسے کچھ پتہ نہیں کہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ ایسے دماغ کے ساتھ کسی چیز کی گہرائی میں اُترے گا تو موتی ملیں گے۔ موتی سمندر کے اوپر نہیں ملتے جب تک آپ غوطہ لگا کے گہرائی میں نہیں جائیں گے، تب تک نہیں ملے گا اور جو گہرائی میں جائے گا اسے اس وقت دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہونا پڑے گا، شمع علم کے لیے پروانہ وار نثار ہونا سیکھیے ! تو آپ کا مقام یہ ہے، اس کو پرانے فضلاء جانتے تھے۔ آج صورت حال تو زمانے کے ساتھ تبدیل ہو ئی وہ افسوسناک ہے؛ لیکن یہ صورت حال سو فیصد نہیں بدلی، بلکہ الحمد للہ آج بھی ہمارے طبقہ میں ایسے ممتاز فضلاء ہیں جو اپنے مقام کو پہچانتے ہیں اور اپنے مقام کے مناسب محنتیں کرتے ہیں، آج اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے آج آپ حضرات کے لیے ان بزرگوں کی برکت سے ہمہ جہت آرام و سکون میسر فرمایا ہے، آپ کے پاس بہترین بیڈ ہیں۔ شاندار کھانے ہیں، اُڑانے کے لیے وظیفے ہیں، ایسی کوئی راحت نہیں جو آپ کو حاصل نہیں، لیکن آپ ان راحتوں سے مولانا فرنگی محلیؒ کا مقام حاصل کرنا چاہیں۔ امام احمد بن حنبلؒ کا مقام حاصل کرنا چاہیں نا ممکن ہے، وہ مقام تو حاصل ہوتا ہے جدوجہد سے اور علم کے پیچھے مرمٹنے سے اور اس کے پیچھے اپنی تمام توانائیاں صرف کرنے سے اور ہر چیز کی گہرائی میں اُترنے سے۔
ہماری آنکھیں تو کل بند ہو جانے والی ہیں، آنے والی دنیا کی زمام آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ مستقبل کے اکابر ہیں۔ اس لیے میرے بھا ئیو! اپنا مقام پہچانو، اپنے وقت کی قدر کرو! جس مقصد کے لیے آپ یہاں آئے ہیں اس کو حاصل کیجیے، ہوش کے ناخن لیجیے، اپنی گتھیاں سلجھائیے، علم میں گیرائی اور گہرائی پیدا کیجیے! فقاہت سے حظِ وافر حاصل کیجیے، اساتذہ کی قدر کیجیے، ان سے خوب استفادہ کیجیے اور منزل کی طرف رواں دواں رہیے۔ منزل دور نہیں ہے۔ منزل آپ کا انتظار کر رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے امانت اٹھائی ہے اور امانت اٹھانے کا بہت اونچا مقام اور درجہ ہے، لہٰذا آپ نے جس درجہ میں امانت اٹھائی ہے اسی درجہ میں اس کا حق ادا کیجیے۔ اللہ نے آپ حضرات کو اعلیٰ درجہ کی استعدادیں دی ہیں اور آپ پر بڑی ذمہ داری عائد کی ہے۔ ہماری آنکھیں تو کل بند ہوجانے والی ہیں۔ آنے والی دنیا کی زمام آپ کے ہاتھ میں ہے، آج آپ اپنے کو تیار نہیں کریں گے؛ کل کی راہنمائی کے قابل اپنے آپ کو نہیں بنائیں گے؛ تو امت کی گاڑی کیسے چلے گی؟ دین کی محنتیں کون کرے گا؟ دین کا صحیح مفہوم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حاصل کیا، صحابہؓ سے تابعینؒ نے حاصل کیا اور نسلاً بعد نسلٍ و قرناً بعد قرنٍ، اُمتاً بعد امۃٍ جو امانت چلی آرہی ہے، دین کا جو صحیح فہم چلا آرہا ہے، اسے حاصل کرنا دین میں فقاہت پیدا کرنا؛ یہی آپ کی زندگیوں کا مقصد ہے۔
میں اُمید کروں گا کہ آپ حضرات اپنے اس مقصد کو سمجھیں گے، اپنے مقام و مرتبہ کو سمجھیں گے، وقت کو ضائع کرنے سے بچیں گے۔ اللہ آپ کے علم میں برکت عطا فرمائے اور اوقات میں برکت عطا فرمائے اور اللہ آپ کو اس قابل بنائے کہ آنے والی امت کی آپ حضرات قیادت کرسکیں اور دین کی امانت جو آپ حضرات کے سپرد ہے، آپ اس کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر دیں،وآخر دعوانا أن الحمد للہ رب العالمین!
(بشکریہ ماہنامہ دارالعلوم دیوبند)