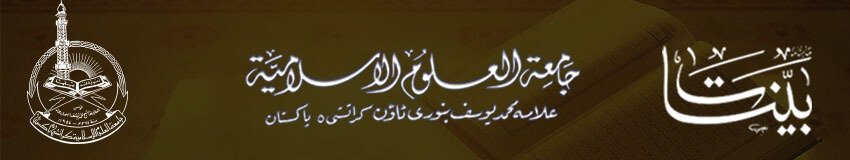
دلائلِ شرعیہ چار ہیں: کتاب، سنت، اجماعِ امت اور قیاس۔
جو امر اِن دلائلِ چہارگانہ میں سے کسی ایک سے بھی ثابت ہو وہ دین میں معتبر ہوگا، ورنہ رَد ہے۔ یہ بھی غلطی ہوگی کہ ان چار میں سے کسی ایک کو نہ مانا جائے اور یہ بھی غلطی ہوگی کہ ان چاروں سے تجاوز کیا جائے۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اجماعِ امت کا حجتِ شرعیہ ہونا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے یا نہیں؟ اس کے جواب کے لیے آپؒ نے چار مرتبہ کلامِ مجید ختم کیا، تویہ آیت خیال میں آئی :
’’وَمَنْ یُّشَاقِقِ الرَّسُوْلَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَہٗ الْہُدٰی… ۔‘‘
ترجمہ: ’’اور جوکوئی مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب کہ کھل چکی اس پر سیدھی راہ۔‘‘
جس سے اجماع کا حجتِ شرعیہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔
اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ کسی عصر کے جمیع علماء کسی امرِ دینی پر اتفاق کرلیں اور اگر کوئی عمداً یا خطاً اس اتفاق سے خارج رہے تو اس کے پاس کوئی دلیل محتملِ صحت نہ ہو اور خطا میں وہ معذور بھی ہوگا۔ غرض مطلقاً عدمِ شرکت مضرِ تحققِ اجماع نہیں، ورنہ قرآن مجید کے یقیناً محفوظ اور متواتر ہونے کا دعویٰ مشکل ہوجائے گا، کیونکہ احادیثِ بخاری سے ثابت ہے کہ حضرت ابی ( رضی اللہ عنہ ) آیاتِ منسوخۃ التلاوۃ کو داخلِ قرآن اور حضرت ابودرداء( رضی اللہ عنہ ) سورۃ اللیل کی آیت: ’’ وَمَا خَلَقَ الذَّکَرَ‘‘ میں کلمہ ’’وَمَا خَلَقَ‘‘ کو اور ابن مسعود( رضی اللہ عنہ ) معوذتین کو خارجِ قرآن سمجھتے تھے،حالانکہ ایک ساعت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی قائل نہیں، بلکہ سب اس کو تمام ازمنہ کے اعتبار سے یقینی اور محفوظ سمجھتے رہے اور چونکہ ان حضرات کو استدلال میں یقیناً غلطی ہوئی، اس لیے کسی نے سلفاً وخلفاً اس کو مضر ومخلِ اجماع نہیں سمجھا، البتہ ان کو بھی شبہ کی وجہ سے معذور سمجھا۔
یاتو مراد اجماع سے اتفاقِ اکثرِ امت ہے اور گو ایسا اجماع ظنی ہوگا، مگر دعوائے ظنی کے اثبات کے لیے دلیلِ ظنی کافی ہے اور ہر اختلاف فلاحِ اجماع نہیں۔
’’فَاعْتَبِرُوْا یَا اُوْلِی الْاَبْصَارِ‘‘ … ترجمہ: ’’سو عبرت پکڑو اے آنکھ والو!۔‘‘ یہ آیت بتلارہی ہے کہ قیاس بھی حجت ہے، حجتِ شرعیہ صرف قیاسِ فقہی ہے، جس کا حاصل بضرورتِ عمل اشتراکِ علت کی وجہ سے حکم کا تعدیہ کرنا ہے مقیس علیہ سے مقیس کی طرف اور چونکہ اصل حکم منصوص میں بھی مؤثر ہے اور وہی علت ہے اور وہ مقیس میں بھی پائی جاتی ہے، اس لیے اس کے حکم کو بھی نص کی طرف مستند کیا جاتا ہے۔
قیاس مظہر ہوتا ہے اور مثبت نص ہی ہوتی ہے، جیسے ’’کل مسکر حرام‘‘ ہے اور افیون بھی مسکر ہے، (اس لیے) وہ بھی حرام ہے، پس مثبت حرمتِ افیون کی بھی نص ہی ہوگی۔
جس امر میں نص ہو اگر وہ احکامِ فقہیہ جواز میں سے ہے تو اس میں قیاس کرنا ’’فَاعْتَبِرُوْا یَا اُوْلِی الْاَبْصَارِ‘‘ … ترجمہ: ’’سو عبرت پکڑو اے آنکھ والو!۔‘‘ وغیرہ نصوص سے مامور بہ ہے اور اگر وہ احکامِ شرعیہ سے نہ ہو تو اس میں قیاس کرنا’’ لَاتَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِہٖ عِلْمٌ‘‘… وغیرہ نصوص سے منہی عنہ ہے۔
کیا ملائکہ اور مجذوبین بھی قیاس کرتے ہیں اور ان کا اجتہاد غلط بھی ہوسکتا ہے؟
فرمایا: میرا رجحان پہلے اس طرف تھا کہ مجذوبین اجتہاد نہیں کرتے، محض امرِ صریح کے متبع ہیں اور ملائکہ کے متعلق بھی خیال تھا کہ وہ بھی محض نصوص کے متبع ہیں، مگر حدیث جبرئیل ’’إنہٗ دس الطین في فم فرعون مخافۃ أن تدرکہ الرحمۃ‘‘ (روایت بالحاصل) نیز حدیث ’’القاتل التائب من الذنب اختلف فیہ ملائکۃ الرحمۃ والعذاب‘‘ سے اس طرف رجحان ہوگیاہے کہ ملائکہ اجتہاد بھی کرتے ہیں، وکذا المجذوبین وزاد الرجحان بقصۃ الإشراق أن المجذوبین مختلفون في أحکام بقاء السلطنۃ وتبدلہا۔
واقعۂ حدیث:’’ القاتل التائب من الذنب‘‘ یا توبہ میں اختلاف تھا، اس لیے ملائکہ نے اجتہاد کیا جو فیصلہ کے وقت ایک غلط بھی ثابت ہوا، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ بھی اجتہاد کرتے ہیں اور اُن کا اجتہاد غلط بھی ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ملائکہ کو بعض اوقات قواعدِ کلیہ بتادیئے جاتے ہیں، جب ہی تو ان کو اجتہاد کی نوبت آئی۔
علمِ اعتبار کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مشبہ کو دوسرے مشبہ بہ سے واضح کیا جائے، ثابت نہ کیا جائے، بلکہ مشبہ دلیلِ آخر سے ثابت ہے اور یہ نہ مجاز میں داخل ہے خواہ مجاز مرسل ہو خواہ استعارہ، کیونکہ مجاز میں موضوع لہٗ کے مراد نہ ہونے پر قرینہ ہوتا ہے، اس لیے غیر موضوع لہٗ مراد ہوتا ہے اور یہاں نہ موضوع لہٗ کے غیر مراد ہونے کا کوئی قرینہ ہے، نہ غیر موضوع لہٗ مراد ہے اور نہ یہ کنایہ میں داخل ہے، کیونکہ کنایہ میں معنیٰ موضوع لہٗ متروک نہیں ہوتے، بلکہ کلام کا مدلول اصلی وہی موضوع لہٗ ہوتا، مگر مقصود اس کا لازم یا ملزوم ہوتا ہے، جیسے: ’’ طویل النجاد‘‘ کہ اس میں مدلولِ وضعی متروک نہیں، مدلولِ کلام وہی ہے، مگر مقصود ’’طویل القامۃ‘‘ ہے، کیونکہ ’’طویل النجاد‘‘ کے لیے ’’طویل القامۃ‘‘ لازم ہے اور اعتبار میں وہ معنی نہ مقصود ہے نہ مدلولِ کلام ہے، پس یہ اعتبار گویا قیاسِ تصرفی ہے اور مشابہ ہے قیاسِ فقہی کے، مگر عین قیاسِ فقہی نہیں، کیونکہ قیاسِ فقہی میں علتِ جامعہ مؤثر ہے حکمِ مقیس میں، اس لیے وہ حکم منسوب الی القیاس ہوتا ہے، یہاں یہ بھی نہیں ہے، صرف مقیس مقیس علیہ میں تشابہ ہے اور اس مشابہت کو حکم میں کوئی اثر نہیں، بلکہ وہ حکم خود مستقل دلیل سے ثابت ہے، یہ حقیقت ہے علمِ اعتبار کی۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے’’ اِعْلَمُوْٓا أَنَّ اللّٰہَ یُحْیِ اْلأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِہَا‘‘ کی تفسیر میں فرمایا ہے: ’’لین القلوب بعد موتہا و إلا فقد علم إحیاء الأرض مشاہدۃ‘‘ یعنی یہاں ’’أرض‘‘ سے مراد قلوب ہیں، یہ بھی علمِ اعتبار ہی ہے اور ’’إلا فقد علم إحیاء الأرض‘‘ سے مشہور تفسیر کی نفی کرنا مقصود نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اے مخاطب! تجھ کو اس آیت میں ظاہری مدلول پر اکتفا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ظاہر ہی ہے، بلکہ اس سے قلوب کی طرف انتقال کرنا چاہیے کہ دلوں کی بھی وہی حالت ہے جو زمین کی حالت ہے۔ یہ روایات میرے رسالہ ’’مسائل السلوک‘‘ میں مذکور ہیں۔ ان آثار وغیرہ سے ثابت ہوگیا کہ علمِ اعتبار صوفیاء کی بدعت نہیں، نصوص میں اس کی اصل موجود ہے، پس جو لوگ علمِ اعتبار کی رعایت کرنے میں صوفیاء پر زندقہ اور الحاد کا فتویٰ لگاتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ یہ لطائف ، تاویلات ، نکات کے درجہ میں ہیں، تفسیر نہیں اور ان کو علومِ قرآنیہ نہیں کہہ سکتے۔
غیر مدلولِ قرآنی کو مدلولِ قرآنی پر کسی مناسبت ومشابہت سے قیاس کرلیا جائے، یہ حقیقی قیاس نہیں، محض صورت قیاس کی ہے، اس لیے قیاس کے احکام ثابت نہیں۔ یہ قیاس حجتِ شرعیہ نہیں، اس لیے اس قیاس سے اس حکم کو نص کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں، حجتِ شرعیہ صرف قیاسِ فقہی ہے۔
پھر آگے ان میں ایک تفصیل ہے، جس سے دونوں کا درجہ جدا جدا ہوجاتا ہے۔ وہ یہ کہ اگر غیر مدلولِ قرآنی مقصودِ دینی ہے تو اس (صوری) قیاس کادرج علمِ اعتبار ہے اور وہ معمول اُمت کا رہا ہے، بشرطیکہ اس کو درجۂ تفسیر تک نہ پہنچا یا جائے۔ اور اگر وہ غیر مدلولِ قرآنی مقصودِ دنیوی ہے تو اس قیاس کا درجہ فال متعارف یا شاعری سے زیادہ نہیں، گو مقیس صحیح ہی ہو یا اتفاق سے صحیح ہوجائے۔ پس جو درجہ اس شاعری یا اس تفاول کا ہے، یہی درجہ اس قیاس متکلم فیہ کا ہے۔
ایک علم جو بوجہ انتساب الی الصلحاء اس ( تفاول وشاعری) سے بھی اشرف ہے، یعنی تعبیرِ رؤیا، اس کامدار بھی ایسے ہی مناسبات پر ہے، اس کو بھی نہ کوئی قابلِ تحصیل سمجھتا ہے اور نہ کسی درجہ میں اس کو حجت سمجھتا ہے۔
علمِ اعتبار علمِ تعبیر سے بھی اشرف ہے اور اشرف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تعبیر سے تو فقط احکامِ تکوینیہ پر استدلال کیا جاتا ہے اور علمِ اعتبار سے خالص احکامِ شرعیہ پر (استدلال کیا جاتاہے، اس لیے علمِ اعتبار) دو درجہ اشرف ہوا۔
علمِ اعتبار یہ ہے کہ دوسرے کے قصہ کو اپنی حالت پر منطبق کرکے سبق حاصل کیا جائے، دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استحضار کیا جائے اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے۔
ایسے استنباطات کا درجہ فقہی قیاس سے بھی کم ہے، نہ وہ اشارات یقینی ہیں، نہ ان سے تعبیر مقصود ہے، خود وہ علم بھی قابلِ تحصیل نہیں، بلکہ بلاتحصیل ہی جس کے ذہن کوان مناسبات سے مناسبت ہوگی، وہ ایسے استدلالات پر قادر ہوگا، گو علم وفضل میں کوئی معتدبہ درجہ نہ رکھتا ہو۔
خلاصہ یہ ہے کہ فقہی قیاس میں تو غیر منصوص کو منصوص کے ساتھ لاحق کرکے اس پر حکم کرتے ہیں اور وہ بھی جہاں مستقل دلیل نہ ہو، یہ غیر منصوص بھی علت کے واسطے سے نص کا مدلول ہوتا ہے اور قیاس محض مُظہر ہے۔ اور صوفیاء کے قیاسات (علمِ اعتبار) اگر اور دلیل سے ثابت نہ ہوں تو ان نصوص سے ثابت ہی نہیں ہوتے، یہ اعتبار محض ایک تشبیہ کا درجہ ہے، جس میں وجۂ تشبیہ مؤثر فی الحکم نہیں ہوتی۔
استدلال تو مفہومِ لغوی سے ہوتا ہے، ان طرق کے ساتھ جو اہلِ معانی واصول نے بیان کیے ہیں اور اعتبار تشبیہ واشارہ کے طور پر ہوتا ہے۔
اور ان دونوں کی اصل قرآن سے ثابت ہے، دوسرے طریق کا نام خود قرآن ہی میں آیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے: ’’فَاعْتَبِرُوْا یٰاُوْلِیْ اْلاَبْصَارِ‘‘ اس سے اوپر بنو نضیر کے جلاوطن کیے جانے کا قصہ مذکور ہے، جس کے بیان کرنے کے بعد یہ فرمایا ہے کہ اے بصیرت والو! عبرت حاصل کرو، یعنی اگر تم ایسی حرکت کروگے، جو ان لوگوں نے کی ہے تو اپنے واسطے بھی اس عذاب کو تیار سمجھو اور یہی تو علمِ اعتبار ہے کہ دو چیزوں میں مشابہت ہو تو ایک نظیر سے دوسری نظیر کا استحضار کیا جائے اور یہی عبرت حاصل کرنے کے معنی ہیں کہ دوسرے کی حالت کو اپنے اوپر منطبق کیا جائے۔
’’اِذْہَبْ إِلٰی فِرْعَوْنَ إنَّہٗ طَغٰی‘‘کے تحت صوفیاء نے لکھا ہے:’’ اذہب یا روح! إلی النفس وجاہدہا إنہا قد طغت‘‘کہ اے روح! نفس کی طرف جا اور اس سے جہاد کرکے اس کو مغلوب کر کہ وہ حد سے نکلا جارہا ہے۔ صوفیاء کی مراد تفسیر کرنا نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اے قرآن پڑھنے والے! تو قرآن کے قصوں کو محض قصہ سمجھ کر نہ پڑھ، بلکہ ان سے سبق حاصل کر، کیونکہ قرآن کریم میں جو قصے ہیں وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کیے گئے ہیں:’’ لَقَدْ کَانَ فِیْ قَصَصِہِمْ عِبْرَۃٌ‘‘ پس جب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ پر پہنچے تو اس سے یہ سبق حاصل کر کہ تیرے اندر بھی ایک چیز موسیٰ کے اور ایک چیز فرعون کے مشابہ ہے، یعنی روح اور نفس، ایک داعی الی الخیر ہے جو مشابہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہے، دوسرے داعی الی الشر ہے جو مشابہ فرعون ملعون کے ہے، پس تو بھی اپنے روح کو نفس پر غالب کر اور نافرمانیوں سے باز آجا، یہ علمِ اعتبار ہے کہ دوسرے کے قصہ کو اپنی حالت پر منطبق کرکے سبق حاصل کیا جائے۔
رہا یہ سوال کہ جس طرح صوفیاء نے علمِ اعتبار کا استعمال کیا ہے، کیا نصوص میں بھی استعمال آیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ بحمد اللہ! اس کی نظیر نصوص میں بھی موجود ہے اور میں یہ بات خود نہیں کہتا، بلکہ شاہ ولی اللہ صاحبؒ کے قول سے میں اس کا ثبوت دیتا ہوں، اتنے بڑے محقق نے دو حدیثوں کے متعلق ’’الفوز الکبیر‘‘ میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تقدیر کا مسئلہ ارشاد فرمایا:
’’ما منکم من أحد إلا وقد کتب لہٗ مقعدہٗ من النار ومقعدہٗ من الجنۃ، قالوا: یا رسول اﷲ! أفلا نتکل علی کتابنا وندع العمل؟۔‘‘ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اعملوا فکل میسر لما خلق لہٗ، أما من کان من أہل السعادۃ فسیُیَسر لعمل السعادۃ۔‘‘ اس کے بعد آپ نے یہ آیت پڑھی: ’’فَاَمَّا مَنْ اَعْطیٰ وَاتَّقیٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی فَسَنُیَسِّرُہٗ لِلْیُسْریٰ وَاَمَّا مَنْ بَخِلَ الایۃ۔‘‘
اب اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس آیت میں تقدیر کا ذکر کہاں ہے؟ آیت کا مدلول تو یہ ہے کہ اعطاء وتقویٰ سے جنت آسان ہوجاتی ہے اور بخل واستغناء سے دوزخ آسان ہوجاتی ہے۔ اس کا جواب شاہ صاحبؒ نے دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علمِ اعتبار کے اس آیت کے مضمون سے حدیث کے مضمون پر استشہاد فرمایا ہے اور مقصود تشبیہ دینا ہے کہ جیسے بواسطہ بعض اعمال کے بعض کے لیے جنت اور بعض کے لیے دوزخ کو آسان کردیا جاتا ہے، اسی طرح بواسطہ تقدیر کے بعض کے لیے اعمالِ صالحہ کو، بعض کے لیے معاصی کو آسان کردیا ہے اور یہ تشبیہ محض توضیح کے لیے ہے کہ تقدیر سے تیسیر ویسی ہی ہوجاتی ہے جیسی اس آیت میں تیسیر اعمال سے مذکور ہے، پس مقصود تشبیہ سے توضیح ہے، شاہ صاحبؒ نے حدیث کی شرح میں علمِ اعتبار کی اصل قرآن سے بتلائی ہے۔
حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمِ اعتبار کا استعمال فرمایا ہے، بڑے شخص کے سر رکھ کر میں یہ کہہ رہا ہوں، خود اتنی بڑی بات نہیں کہتا، کیونکہ یہ بڑا دعویٰ ہے اور اگر کوئی شاہ صاحبؒ کے قول کو نہ مانے تو میں اس سے کہوں گا کہ پھر وہ ان حدیثوں کی شرح کردے، یقیناً ان حدیثوں میں کوئی علمِ وہبی ہے، وجہِ ربط بجز اس کے جو شاہ صاحبؒ نے فرمایا، بیان نہ کرسکے گا۔ (جاری ہے)