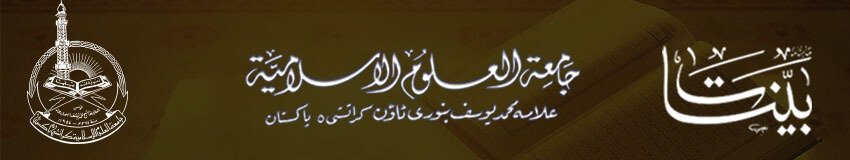
واقعہ یہ ہے کہ ہر پیغمبر کو اپنی امت کے ساتھ، بلکہ ہر مقتدیٰ کو اپنے متبعین اور منتسبین کے ساتھ ایک خاص قسم کی شفقت ومہربانی کا تعلق ہوتاہے، جس طرح ہر شخص کو اپنی اولاد کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتاہے جو دوسرے انسانوں کے ساتھ نہیں ہوتا اور اس تعلق کی وجہ سے ان کی قدرتی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پائیں۔ اس شفقت ورأفت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں سے بڑھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعلق صرف ایسا نہیں ہے کہ بات کہہ کر بے تعلق ہوگئے، بلکہ آپ کا اپنی اُمت سے قلبی تعلق ہے، ظاہراً بھی کہ آپ ان کے ہمدرد ہیں اور باطناً بھی امت کو جو تکلیف ہوتی ہے اس میں آپ بھی شریک ہوتے تھے، اور ان میں سے کسی کو تکلیف پہنچ جاتی تو آپ کو کڑھن ہوتی تھی، عیادت کے لیے تشریف لے جاتے، دوا بتاتے، مریض کو تسلی دینے کی تعلیم دیتے تھے، تکلیفوں سے بچانے کے لیے ان اُمور کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش ہے جو مختلف مواقع پر آپ سے بار بار ظاہر ہوئی کہ آپ کی اُمت دوزخ میں نہ جائے اور جن کی بدعملی اس درجے کی ہو کہ ان کا دوزخ میں جانا اور کچھ عذاب پانا ناگزیر ہو اُن کو کچھ سزا پانے کے بعد نکالا جائے، چنانچہ درج ذیل آیات، احادیث، روایات اور واقعات سے بخوبی اندازہ لگایاجاسکتا ہے، اس لیے اُمتِ محمدیہ پر لازم ہے کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں اور سب آپس میں رحمت وشفقت کے ساتھ مل کر رہیں اور اپنی معاشرت میں رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کریں:
1: ’’لَقَدْ جَاۗءَکُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ‘‘ (التوبہ:۱۲۸)
ترجمہ: ’’(اے لوگو!) تمہارے پاس ایک ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس (بشر) سے ہیں جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت گراں گزرتی ہے، جو تمہاری منفعت کے بڑے خواہشمند رہتے ہیں۔(یہ حالت تو سب کے ساتھ ہے بالخصوص) ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق ( اور ) مہربان ہیں۔‘‘
اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری خلقِ خدا پر خصوصاً مسلمانوں پر بے حد مہربان وشفیق وہمدرد ہونا بیان فرمایا ہے۔ نیز اس آیت میں اتباعِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ (جواہر القرآن، ج:۲، ص:۴۵۹)
اللہ تعالیٰ نے اس آیتِ مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پانچ قسم کی صفات بیان فرمائی ہیں، جوکہ حسب ذیل ہیں: ۱:- مِنْ اَنْفُسِکُمْ، ۲:- عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ، ۳:- حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ، ۴:-رَءُوْفٌ، ۵:-رَحِیْمٌ۔ (تفسیر کبیر:ج:۶، ص:۱۷۷)
اس صفت کو ذکر کرنے سے مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی وحسبی طہارت وپاکیزگی وبلندی کو بیان کرنا ہے، گویا یہ کہا گیا کہ تمہارے قبیلے وخاندان سے ہیں، جس کے حالات صدق وامانت، عفت، صیانت ودیانت ابتداء عمر سے تمہیں معلوم ہے، کوئی غیر نہیں جس سے واقف نہ ہوں۔ اور نیز یہ کہ تمہارے ملک اور تمہاری قوم کا شخص ہے، جو تمہارے لیے باعثِ فخر ورحمت ہے۔ بعض نے ’’اَنْفُس‘‘ کو ’’نَفِیْس‘‘ سے لیا ہے، یعنی سب سے افضل واشرف ہے۔ (تفسیر کبیر، ج:۶، ص:۱۷۷۔ تفسیر حقانی، ج:۲، ص:۵۲۵)
۱: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے قبائل کی شاخ میں بہترین شاخ سے مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ میں اس قرن (شاخ) سے پیدا ہوا جو میرا ہے۔ (بخاری شریف، ج:۱، ص:۵۵۳)
۲: حضرت واثلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اللہ تعالیٰ نے نسل اسماعیل سے کنانہ کو منتخب فرمایا اور بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب فرمایا اور قریش میں سے بنوہاشم کو منتخب فرمایا اور مجھے بنوہاشم میں سے منتخب فرمایا۔‘‘ (مسلم شریف، ج:۲، ص:۲۴۵۔ ترمذی، ج:۲، ص:۲۰۲)
۳: حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ’’اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا فرمایا اور ان کی شاخیں بنائیں، مجھے بہترین شاخ میں رکھا۔ پھر قبائل بنائے اور بہترین قبیلے میں رکھا اور پھر گھرانے بنائے اور مجھے بہترین گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں ان سب سے بہترین ذات اور بہترین گھرانے کا ہوں۔‘‘ (ترمذی، ج:۲، ص:۲۰۱)
۴:علامہ ابن کثیرؒ لکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت نجاشیؒ کے سامنے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کسریٰ کے سامنے آپ کے حسب ونسب کو ان الفاظ میں بیان فرمایا تھا: ’’إن اللہ بعث فینا رسولاً منا نعرف نسبہ وصفتہ ومدخلہ ومخرجہ وصدقہ وأمانتہ۔‘‘ یعنی’’ اللہ تعالیٰ نے ہم میں ایک رسول بھیجا ہے جو ہم میں سے ہے ہم اس کے نسب اور اس کے حالات کو جانتے ہیں، ہم ہر طرح سے اس کی سچائی اور امانت کو جانتے ہیں۔‘‘ (تفسیر ابن کثیر، ج:۲، ص:۴۶۳)
۵:قیصر روم نے جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے متعلق یہ سوال کیا کہ: ’’کیف نسبہ فیکم؟‘‘ ان کا نسب کیسا ہے؟ حضرت ابوسفیانؓ نے فرمایا کہ: ’’ہو فینا ذو نسب وہو في حسب ما لایفضل علیہ أحد، قال: ہٰذہٖ آیۃ۔‘‘ یعنی ’’وہ ہم میں اعلیٰ نسب والے ہیں اور اعلیٰ حسب والے ہیں، نسب وحسب خاندان میں کوئی اُن سے بڑھ کر نہیں، قیصر روم نے کہا کہ: یہ بھی ان کے نبی ہونے کی علامت ہے۔‘‘ (سیرۃ المصطفیٰ، ج:۱، ص:۱۶)
۶:حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ: عرب کے قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسبی تعلق تھا۔ (بخاری، ج:۱، ص:۴۹۶۔ مظہری، ج:۵، ص:۴۵۳)
۷: حضرت جعفر صادقؒ نے فرمایا کہ: حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری دور تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے آباء واجداد جاہلیت کے نکاح کے طریقوں سے پاک رہے۔(مظہری، ج:۵ص: ۴۵۲)
عز یعزبکسر العین (ض) معنی شاق اور سخت کے ہوتے ہیں۔ ’’مَا عَنِتُّمْ‘‘ میں ما زائدہ ہے، مصدر کے معنی میں ہے۔ ’’عنۃ‘‘ (س) جس سے ’’عَنِتُّمْ‘‘ بناہے کے معنی مشقت، فساد، ہلاکت خطا کے ہیں، یعنی تمہارا دشواری ودکھ میں پڑ جانا اور گمراہ ہوجانا، ہلاک ہونا، جسمانی، روحانی، مالی مشکلات میں مبتلا ہوجانا، اور تمہارا حق سے منہ موڑنا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت گراں گزرتاہے۔
واضح ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت 1:مؤمنین، 2: کفار، 3: منافقین تینوں کے حق میں تھی، جس کی تفصیل حسب ذیل ہے:
1: ’’مؤمنین‘‘ کے حق میں بھی شفقت فرماتے تھے کہ: ایمان کی برکت سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے ان پر دائمی عذاب نہ ہوگا، لیکن معصیت سے بھی تکلیف ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ تکلیف بھی اُن کو نہ پہنچے۔
2:’’منافقین‘‘: کا نفاق بھی آپ پر بڑا ہی شاق گزرتا تھا، محض دنیا کے لیے بے ہودہ نہ اِدھر کے نہ اُدھر کے بن کر، کھلے کافروں سے باطن میں بدتر ہو رہیں کہ انجام ان کا کفار کی طرح دائمی عذاب ہوگا۔
3: ’’کفار‘‘: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو کفر وشرک میں دیکھتے اور یہ خیال فرمایا کرتے کہ یہ لوگ کس انجامِ بدکا شکار ہونے والے ہیں، یہ لوگ کیوں کر اپنے ہاتھوں اپنے لیے ہلاکت کا کنواں کھود رہے ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلِ رحم پرور کو نہایت صدمہ ہوتا تھا۔ بسا اوقات یہ کیفیت اس قدر بڑھ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی وتسکین کے لیے اپنا کلام وپیغام بھیجنا پڑتا، چنانچہ سورۂ’’ یس‘‘ میں ہے: ’’فَلَا یَحْزُنْکَ قَوْلُہُمْ۰ۘ اِنَّا نَعْلَمُ مَا یُسِرُّوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ‘‘ یعنی ’’ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہونی چاہئیں۔ بے شک ہم سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ یہ دل میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔‘‘ نیز سورۂ آل عمران میں ہے: ’’وَلَا یَحْزُنْکَ الَّذِیْنَ یُسَارِعُوْنَ فِی الْکُفْرِ‘‘ یعنی ’’کفر میں بڑھ بڑھ کر حصہ لینے والوں کی حالت سے آپ غمگین نہ ہوں۔‘‘ اسی طرح سورۃ یونس میں ہے: ’’وَلَا یَحْزُنْکَ قَوْلُہُمْ‘‘ یعنی ’’اور آپ کو اُن کی باتیں غم میں نہ ڈالیں۔‘‘
اسی طرح سورۃ الحجر میں ہے: ’’وَلَا تَحْزَنْ عَلَیْہِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَکَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ‘‘ یعنی ’’اور کافروں کا کچھ غم نہ کریں اور مسلمانوں پر شفقت رکھئے۔‘‘ اسی طرح سورۃ المائدہ (۴۱) میں ہے: ’’يٰٓاَيُّھَا الرَّسُوْلُ لَا يَحْزُنْکَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِيْ الْکُفْرِ‘‘ یعنی ’’اے رسول! جو لوگ کفر میں دوڑ دوڑ کر رہتے ہیں وہ آپ کو مغموم نہ کریں۔‘‘ اس طرح سورۃ الانعام (۳۳) میں ہے: ’’قَدْ نَعْلَمُ اِنَّہٗ لَيَحْزُنُکَ الَّذِيْ يَقُوْلُوْنَ فَاِنَّہُمْ لَا يُکَذِّبُوْنَکَ وَلٰکِنَّ الظّٰلِمِيْنَ بِاٰيٰتِ اللہِ يَجْحَدُوْنَ‘‘ یعنی ’’ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ کو ان کے اقوال مغموم کرتے ہیں، سو یہ لوگ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے ،لیکن یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔‘‘ اسی طرح سورۃ لقمان (۲۳) میں ہے: ’’وَمَنْ کَفَرَ فَلَا يَحْزُنْکَ کُفْرُہٗ ۭ اِلَيْنَا مَرْجِعُہُمْ‘‘ یعنی ’’اور جو شخص کفر کرے سو آپ کے لیے اس کا باعث غم نہ ہونا چاہیے، ان سب کو ہمارے پاس ہی لوٹنا ہے۔‘‘ اسی طرح سورۃ النحل (۱۲۷) میں ہے: ’’وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْہِمْ وَلَا تَکُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْکُرُوْنَ‘‘ یعنی ’’ان پر غم نہ کیجئے اور جو کچھ یہ تدبیر کیا کرتے ہیں اس سے دل تنگ نہ فرمائیں۔‘‘اسی طرح سورۃ الحجر (۹۷-۹۸) میں ہے: ’’وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّکَ يَضِيْقُ صَدْرُکَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَکُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ‘‘ یعنی ’’اور واقعی ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں، اس سے آپ تنگ دل ہوتے ہیں۔ سو (اس کا علاج یہ ہے کہ) آپ اپنے پروردگار کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے اور نماز پڑھنے والوں میں رہیے۔
جب ’’حرص‘‘ کا استعمال ’’عَلٰی‘‘ کے صلہ سے کیا جاتا ہے تو اس کے معنی شدتِ طلب کے ہوتے ہیں، اس لیے آیت کا ترجمہ یہ ہوا کہ ہمارا نبی تو لوگوں کی نفع رسانی کا کمال طالب وشائق ہے۔ آیتِ بالا سے واضح طریقے سے ثابت ہوتاہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع آدم کے مفاد اور رفاہ وصلاح کی آرزو بہ درجۂ کمال تھی۔ چنانچہ سورۂ یوسف (۱۰۴) میں ہے: ’’وَمَآ اَکْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِيْنَ‘‘ یعنی ’’بہت لوگ ہیں جو ایمان نہیں لائیں گے، اگرچہ تجھ کو ان سے ایمان لے آنے کی بڑی چاہت ہے۔‘‘ نیز سورۃ النحل (۳۷)میں ہے کہ: ’’اِنْ تَحْرِصْ عَلٰي ہُدٰیہُمْ‘‘ سو اُن کے راہِ راست پر آنے کی آپ کو تمنی ہو تو (کچھ نتیجہ نہیں)، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں کرتا جس کو گمراہ کرتاہے اس کے عناد کی وجہ سے، ’’وقیل: حریص علی إیصال الخیرات لکم في الدنیا والآخرۃ‘‘ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اس بات کے حریص ہیں، ان کو دنیا وآخرت کی تمام بھلائیاں نصیب ہوں۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منتہائے نظر اور کمال آرزو یہ ہی تھا کہ تمام عالم کے سر ایک ہی مالک وحدہٗ لاشریک لہ کے سامنے جھکے ہوئے ہوں۔ ربِ واحد کا دین واحد ہی تمام اصناف انسانی کو متحد ومتفق بنانے والا ہو۔ ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں پر نظر ڈالو، جو وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اُمت کے حق میں فرمائی ہیں، وفات سے ایک ماہ پہلے ایک خطبہ کے آغاز میں فرمایا:
’’مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہیں سلامتی سے رکھے، تمہاری حفاظت فرمائے، تمہیں شر سے بچائے، تمہاری مدد کرے، تم کو بلند کرے، ہدایت اور توفیق دے، اپنی پناہ میں رکھے، آفتوں سے بچائے، تمہارے دین کو تمہارے لیے محفوظ بنائے۔‘‘ ذرا ان الفاظ پر غور کرو، ایک کے بعد دوسری دعا اور دوسری کے بعد تیسری گویا دعا وبرکت دیتے تھکتے ہی نہیں، یہ اسی صفت ’’حَرِیْصٌ عَلَیْکُمْ‘‘ کا ظہور ہے۔ (رحمۃ للعالمین، ج:۲، ص:۷۹)
صفاتِ بالا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ’’رَءُوْفٌ‘‘ اور ’’رَحِیْمٌ‘‘ کے اسماء سے یاد فرمایا گیا ہے۔ ’’رَءُوْفٌ‘‘ رأفت سے مبالغہ کا صیغہ ہے، چنانچہ تفسیر قرطبی ج:۸، ص:۲۷۴ میں ہے: ’’الرؤف المبالغ في الرأفۃ والشفعۃ‘‘ اور یاد رکھنا چاہیے کہ جو صیغے مبالغہ کے اوزان پر آتے ہیں، وہ معنی کثرت وفراوانی کا ادا کرتے ہیں۔ ’’رَحِیْمٌ‘‘ رحم سے صفتِ مشبہ کا صیغہ ہے اور جو صیغے صفتِ مشبہ کے اوزان پر آتے ہیں، صفت لازم اور معنی ثابت کے مظہر ہوتے ہیں، لہٰذا ’’رَحِیْمٌ‘‘ کے معنی دائم الرحمت کے ہیں، چنانچہ سورۃ الحج (۶۵) اور سورۂ بقرہ (۴۳) میں ہے: ’’إِنَّ اللہَ بِالنَّاسِ لَرَؤٗفٌ رَّحِیْمٌ‘‘ یعنی ’’اللہ تعالیٰ انسانوں پر رؤف ورحیم ہے۔‘‘ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ امر نہایت شرف وعنایت، تکریم وحرمت کا موجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں وہ دو نام بہ حالتِ ترکیبی تجویز فرمائے گئے جو اس ترکیب کے ساتھ ساتھ خود ذات پاک سبحان کے لیے مستعمل ہوئے ہیں۔ (رحمۃ للعالمین، ج:۲، ص:۸۰)
ذیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصفِ رأفت (شفقت) ورحمت کے چند نمونے بطور ایمان کی تازگی کے لیے درج کیے جاتے ہیں۔
۱: ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ: ’’کان رسول اللہ ﷺ یتأخر لنا بالموعظۃ مخافۃ السامۃ علینا۔‘‘ (مسلم، ج:۲، ص:۲۷۷) یعنی ’’نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گاہ بہ گاہ (کبھی کبھی) وعظ سنایا کرتے تھے، اس اندیشے سے کہ روزانہ سننا ہم پر گراں نہ گزرے۔‘‘ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصول ازراہِ شفقت ورأفت تھا کہ سامعین جس قدر بھی سنیں نشاطِ طبع اور حضورِ قلب سے سنیں اور آئندہ کے لیے شوق تمام باقی رہے۔
۲: عادتِ مبارکہ تھی جب بہ حالتِ نماز کسی بچے کے رونے کی آواز سن پاتے تو ہلکی فرمادیتے کہ ماں بچے کو جلد سنبھال سکے۔ (مسلم، ج:۱، ص:۱۸۸) آپ کا یہ عمل بھی شفقت کا مظہر تھا۔
۳:عادتِ مبارکہ تھی کہ سوار ہوکر کسی کو پیادہ ہمرکاب چلنے کی اجازت نہ فرماتے تھے، اگرچہ بہت سے فدائی اس خدمت کے تمنائی رہتے، یا تو اسے سوار کرالیتے تھے، یا واپس لوٹا دیتے تھے۔
۴:عادتِ مبارکہ تھی کہ جب کوئی مسلمان مقروض مرجاتا تھا تو اس کا قرض بیت المال سے قبل از تدفین ادا فرما دیتے تھے۔
۵: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: کسی کی غیبت میرے سامنے مت کرو، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی طرف سے میری صاف دلی میں فرق آئے۔
۶: بارہا ایسا بھی ہوا کہ ساری ساری رات اُمت کے حق میں دعا کرتے ہوئے گزرجاتی تھی۔ (ترمذی، ج:۱، ص:۱۰۱، باب ماء جاء في القرأۃ في اللیل)
۷: چھوٹے بچوں کو پیار کرتے، ان کو خود سلام کیا کرتے تھے، ان کے سر پر دستِ شفقت رکھتے۔ گلی میں کھیلتے ہوئے بچوں کو اپنی سواری کے پیچھے سوار کرلیتے تھے۔ غلاموں کے ساتھ سفید زمین پر بیٹھ کر کھانا کھانے میں شامل ہوجاتے۔ (رحمۃٌ للعالمین، ج:۲، ص:۸۱)
۸: جب کسی معاملے میں دو صورتیں سامنے آتیں تو آسان صورت کو اختیار فرماتے تھے۔ (صحیح بخاری، ج:۲، ص:۵۵۳، باب صفۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ۔ صحیح مسلم ، ج:۲، ص:۲۵۶)
۹:عبادتِ نافلہ چھپ چھپ کر ادا فرماتے تھے، تاکہ اُمت پر اس قدر عبادت کرنا شاق نہ ہو۔
۱۰:ایک بار سورج گرہن ہوا، نمازِ کسوف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور یوں دعا فرماتے تھے: ’’رب ألم تعددني أن لاتعذبہم وأنا فیہم وہم یستغفرون ونحن نستغفرک۔‘‘ (زاد المعاد، ج:۱، ص:۴۹)
۱۱: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر میں رسی لٹکتی دیکھی، پوچھا: یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا: فلاں عورت نے لٹکا رکھی ہے، رات کو عبادت کرتی ہوئی جب اونگھنے لگتی ہے تو اس سے لٹک پڑتی ہے۔ فرمایا: اسے کھول دو اور عبادتِ نافلہ اس وقت تک کرو کہ نشاطِ طبع قائم رہے۔ (بخاری، ج:۱، ص:۱۵۴، باب ما یکرہ من التشدید في العبادۃ)
۱۲: بنی اُسید کی ایک عورت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیاگیا کہ وہ تمام شب عبادت کرتی ہے، فرمایاکہ: ایسا نہ کرو، اعمال بقدرِ طاقت ادا کرو۔ (بخاری، ج:۱، ص:۱۵۴، کتاب التہجد، مسلم، ج:۱، ص:۲۶۷)
۱۳: عبد اللہ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ: میں نے سنا ہے کہ تم راتوں کو برابر جاگتے ہو اور دن کو روزہ برابر رکھتے ہو۔ عبد اللہؓ نے کہا: جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایسا نہ کرو، اگر ایسا کروگے تو آنکھیں کمزور ہوجائیںگی اور جان تھک جائے گی۔ آپ پر آپ کے نفس کا بھی حق ہے، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، بیدار بھی رہو، آرام بھی کرو۔ (بخاری، کتاب التہجد، ج:۱، ص:۱۵۴)
۱۴: صلوٰۃ التراویح کے متعلق صحیح مسلم (ج:۱، ص:۲۶۶) میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشب یہ نماز لوگوں کے ساتھ پڑھی اور تیسری شب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہ لے گئے اور پھر صبح کو فرمایا: ’’مازال بکم صنیعکم حتی خشیت أن تفوض علیکم فتعجزوا عنہا‘‘ اس نماز کے لیے تمہارا آنا اور انتظار کرنا وغیرہ دیکھا، مجھے آنے میں صرف یہ خیال مانع ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کردی جائے۔ (بخاری، ج:۱، ص:۱۵۲، کتاب التہجد، باب تحریص النبي صلی اللہ علیہ وسلم علی قیام اللیل)
۱۵: مسواک کے متعلق صحیح مسلم (ج:۱، ص:۱۲۸) میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ’’لولا أن أشق علی أمتي لأمرتہم بالسواک عند کل صلوٰۃ‘‘ یعنی ’’اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہرنماز کے وقت نماز کے وجوب کا حکم دیتا۔‘‘ چونکہ مشقت کا خوف ہے، اس لیے واجب نہیں کرسکتا۔
۱۶: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ: ’’إن کان رسول اللہ ﷺ لیدع العمل وہو یحب أن یعمل بہ خشیۃ أن یعمل بہ الناس فیفرض علیہم۔‘‘ یعنی ’’نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عمل کو بھی چھوڑ دیتے تھے، جس کا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اس خیال سے کہ لوگ بھی عمل کرنے لگیں گے اور یہ ڈرہوتا، کہیں وہ عمل فرض نہ ہوجائے۔‘‘ (بخاری، ج:۱، ص:۱۵۲، کتاب التہجد، باب تحریض النبي ﷺ علی قیام اللیل)
۱۷: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ تہجد میں تھے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اقتدا کو محسوس فرمایاتو نماز کو ہلکا کردیا۔
۱۸: فرض نماز میں تخفیف کے متعلق بخاری (ج:۱، ص:۹۷) میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ’’إذا صلی أحدکم الناس فلیخفف، فان فیہم الضعیف والقیم والکبیر‘‘ یعنی ’’جب تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تو مختصر کرے، کیونکہ نماز میں کمزور، بیمار اور بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔‘‘ ان کا لحاظ کیاکرو۔
۱۹: صحیح بخاری، ج:۱، ص:۵۵ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شب معراج میں پچاس نمازیںفرض کی گئی تھیں، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ: ’’إن أمتک لاتطیق‘‘ کہ آپ کی امت اتنی عبادت کی طاقت نہیں رکھتی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع الی اللہ فرمایا، تخفیف ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کہا جو پہلے کہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار رجوع الی اللہ فرماتے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانچ نمازیں رہ گئیں۔ اس واقعہ سے دو نتیجے صاف طور پر برآمد ہوتے ہیں:
(الف) نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے فرمان کے کتنے مطاع تھے کہ جب پچاس نمازوں کا حکم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارہ میں ذرا بھی لب کشائی نہیں فرمائی۔
(ب)حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کس قدر مہربان تھے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسے تجربہ کار نبی نے ’’إن أمتک لاتطیق‘‘ کو دہرایا تو فوراً اس پاک فطرت کا ظہور ہوا جو ’’عَزِیْزٌ عَلَیْہِ مَا عَنِتُّمْ‘‘ کے تحت پنہاں تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار رجوع الی اللہ فرمایا۔ (رحمۃٌ للعالمین، ج:۳، ص:۷۶)
۲۰: واقعاتِ بدر میں مذکور ہے کہ جب حملہ آورانِ مکہ قید کر لیے گئے تو رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہ آئی، اِدھر سے اُدھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کروٹیں لیتے رہے، کرب واضطراب نمایاں تھا، ایک انصاری صحابیؓ نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف ہے؟ فرمایا: نہیں، مگر عباس کے کراہنے کی آواز میرے کان میں آرہی ہے، اس لیے مجھے چین نہیں آرہا، انصاری صحابیؓ چپکے سے اُٹھے، عباسؓ کی مشک بندی کھول دی، انہیں آرام مل گیا تو وہ فوراً سوگئے۔ انصاری صحابیؓ پھر حاضرِ خدمت ہوئے، پوچھا کہ اب عباسؓ کی آواز کیوں نہیں آرہی؟ انصاری صحابیؓ بولے کہ میں نے اُن کے بندھن کھول دیئے ہیں۔ فرمایا: جاؤ، سب قیدیوں کے ساتھ ایساہی برتاؤ کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ سب قیدی اب آرام سے ہیں، تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اضطراب دور ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما ہوئے۔ ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ قیدی تھے جنہوں نے (۱۳) تیرہ سال تک متواتر اہلِ ایمان کو ستایا، کسی کو آگ پر لٹایا، کسی کو خون میں نہلایا، کسی کو بھاری پتھروں کے نیچے دبایا، کسی کو سخت اذیتوں کے بعد خاک وخون میں سلادیا تھا اور پھر ان پر نرمی اور یہ سلوک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل وانصاف نے حضرت عباسؓ اور دوسرے قیدیوں میں کوئی امتیازی فرق قائم کرنا پسند نہ فرمایا، یہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی، اور طبعی شفقت ورأفت کا عالم۔ (رحمۃ للعالمین، ج:۳، ص:۷۴)
۲۱: نبوت کے چھٹے سال کا ذکر ہے کہ ایک روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہِ صفا پر بیٹھے ہوئے تھے، ابوجہل وہاں پہنچ گیا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیں اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں سن کرخاموش رہے، اس نے ایک پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پھینک مارا، جس سے خون چلنے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کو خبر ہوئی، وہ ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے، قرابت کے جوش میں ابوجہل کے پاس پہنچے اور اس کے سر پر اس زور سے کمان کھینچ ماری کہ وہ زخمی ہوگیا، حضرت حمزہؓ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے اورکہا: بھتیجے! تم یہ سن کر خوش ہوگئے کہ میں نے ابوجہل سے تمہارا بدلہ لے لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: چچا! میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں!تم مسلمان ہوجاؤ تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ حضرت حمزہؓ اسی وقت مسلمان ہوگئے۔ یہ محبت و شفقت، یہ پیار تو ماں باپ کو بھی اپنی سب اولاد کے ساتھ یکساں نہیں ہوتا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہزار دو ہزار افرادِ امت کے ساتھ تھا۔ (رحمۃٌ للعالمین، ج:۱، ص:۵۸)
2: ’’فَلَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ عَلٰٓی اٰثَارِہِمْ اِنْ لَّمْ یُؤْمِنُوْا بِہٰذَا الْحَدِیْثِ اَسَفًا۔‘‘ (الکہف:۶)
’’اگر انہوں نے اس قرآن پاک کو نہ مانا تو شاید آپ ان کے پیچھے انتہائی غم سے اپنی جان کو ہلاک کردیں گے۔‘‘
شانِ نزول:حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قریش کی ایک جماعت جس میں ربیعہ کے دونوں بیٹے: عتبہ اور شیبہ، ابوجہل بن ہشام، نضر بن حارث، عاص بن وائل اور اسود بن مطلب اور ابو البختری شامل تھے، جمع ہوئے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور آپ سے گفتگو کی اور بالآخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہوکر مجلس سے اُٹھ آئے، تو ان لوگوں کی مخالفت اور نصیحت سے سرتابی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلبی تکلیف ہوئی، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے آیتِ بالا نازل ہوئی۔ (روح المعانی، ج:۸، ص:۲۰۵۔ مظہری، ج:۷، ص:۱۷۱)
’’والغرض تسلیۃ الرسول ﷺ۔‘‘ (تفسیر کبیر، ج:۷، ص:۴۲۶)
’’وفي الآیۃ تسلیۃ لرسول اللہ ﷺ تزیل غمہ وہو شفقۃ عظیمۃ۔‘‘ ( نسیم الریاض، ج:۱، ص:۲۳۶)
’’اَسَفًا‘‘ انتہائی غم وغصہ جیسے کسی کے دوست اس کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں، وہ اس فراق پر صبر نہ کرسکے اور غم سے گھل کر مرجائے۔ یہی حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، آپ کو سردارانِ قریش کے ایمان لے آنے کی انتہائی فکر وخواہش تھی اور ان کی سرتابی سے بہت زیادہ اندوہ وملال تھا، آپ نے انتہائی اندوہ وحسرت کو اس فراق زدہ کے غم سے تشبیہ دی جس کو فراقِ احباب نے جان ہار بنادیا ہو۔(مظہری، ج:۷، ص:۱۷۱)
3: نیز اس مضمون کی ایک آیت سورۃ الشعراء (۳) میں بھی ہے: ’’لَعَلَّکَ بَاخِعٌ نَّفْسَکَ اَلَّا یَکُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ‘‘ شاید آپ اپنی جان کھودیں گے اس وجہ سے کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اس آیت کا نزول بھی اس وقت ہوا کہ جب اہلِ مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ کو یہ بات نہایت شاق گزری، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تمنا اور رغبت تھی کہ اہلِ مکہ مسلمان ہوجائیں، اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔
فائدہ: ’’بخع نفسہ‘‘: اس نے غم میں اپنی جان ہلاک کردی۔ (مظہری، ج:۷، ص:۱۷۱)
r: ’’وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی‘‘ (سورۃ الضحٰی :۵)
’’آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہوجائیں گے۔‘‘
شانِ نزول:حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی: الٰہی! میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا: اے جبرئیل! محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) سے جاکر کہہ دے کہ تیری امت کے معاملہ میں تجھے راضی کردیں گے، تجھ کو دکھ نہ دیں گے۔ (بغوی، ج:۴، ص:۴۹۸۔ مظہری، ج:۱۲، ص:۴۴۰)
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایاکہ: میں اپنی امت کی سفارش کروں گا اور اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا، یہاں تک کہ میرا رب ندا دے گا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ! کیا تو اب راضی ہوگیا؟ میں عرض کروں گا: ہاں! میرے رب! میں راضی ہوگیا۔(مظہری، ج:۱۲، ص:۴۴۵)
جب مذکورہ بالا آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ’’اذاً لا أرضٰی وواحد من أمتي في النار‘‘ (قرطبی، ج:۲۰، ص:۸۷) یعنی ’’اگر میر ی امت میں سے ایک بھی دوزخ میں رہ گیا تو میں راضی نہ ہوں گا۔‘‘ (مظہری، ج:۱۲، ص:۴۴۵) ’’وأیضاً أخرجہ الخطیب في التلخیص ویؤیدہٗ ما في صحیح مسلم۔‘‘ (ج:۱، ص:۱۱۳۔ حقانی، ج:۵، ص:۴۰۰۔ الشفاء، ج:۱، ص:۲۵۸)
حضرت زین العابدینؒ فرماتے ہیں کہ: اے گروہِ اہل عراق! تم کہتے ہو کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ اُمید دلانے والی آیت ’’یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓی اَنْفُسِہِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَۃِ اللہ‘‘ ہے اور ہم اہل بیتؓ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سب سے زیادہ امید آفرین آیت ’’وَلَسَوْفَ یُعْطِیْکَ رَبُّکَ فَتَرْضٰی‘‘ ہے۔ (مظہری، ج:۱۲، ص:۴۴۵)
4: ’’وَمَآ اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَ‘‘ (الانبیاء:۱۰۷)
’’اور ہم نے آپ کو کسی اور بات کے واسطے نہیں بھیجا، مگر دونوں جہانوں پر مہربانی کرنے کے لیے۔‘‘
اس سے ثابت ہوتاہے کہ مقبولین کی برکات بلا اُن کے قصد کے تمام عالم کو پہنچتی ہیں، جیسے آفتاب کی شعاعیں بدوں اس کے قصد وعلم کے سب کو پہنچتی ہیں۔ (بیان القرآن، ص:۶۵۰)
فائدہ: ’’عَالَمِیْنَ‘‘، ’’عَالَم‘‘ کی جمع ہے، جس میں ساری مخلوقات انسان، جن، حیوانات، نباتات، جمادات سب ہی داخل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سب کے لیے رحمت ہونا اس طرح ہے کہ تمام کائنات کی حقیقی روح اللہ کا ذکر اور اس کی عبادت کرناہے، یہ ہی وجہ ہے کہ زمین سے جب یہ روح نکل جائے گی اور زمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہ رہے گا تو ان چیزوں کی موت یعنی قیامت آجائے گی اور جب ذکر اللہ اور عبادت کا ان سب چیزوں کی روح ہونا معلوم ہوگیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان چیزوں کے لیے رحمت ہونا بھی خود بخود ظاہر ہوگیا، کیونکہ اس دنیا میں قیامت تک ذکر اللہ اور عبادت آپ ہی کے دم قدم اور تعلیمات سے قائم ہے۔ (معارف القرآن، ج:۶، ص:۳۳۴)
اگر کوئی بدبخت اس رحمتِ عامہ سے خود ہی منتفع نہ ہو تو یہ اس کا قصور ہے، آفتابِ عالم تاب سے روشنی اور گرمی کا فیض ہرطرف پہنچتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص اپنے اوپر تمام دروازے اور سوراخ بند کرلے تو یہ اس کی دیوانگی ہوگی، آفتاب کے عمومِ فیض میں کوئی کلام نہیں ہوسکتا۔ اور یہاں تو رحمۃٌ للعالمین کا حلقۂ فیض اس قدر وسیع ہے کہ جو محروم القسمت مستفید نہ ہونا چاہے اس کو بھی کسی نہ کسی درجہ میں بے اختیار رحمۃٌ للعالمین کا حصہ پہنچ جاتاہے، چنانچہ دنیا میں علومِ نبوت اور تہذیب وانسانیت کے اصول کی عام اشاعت سے ہر مسلم وکافر اپنے اپنے مذاق کے موافق فائدہ اُٹھاتاہے۔ (تفسیر عثمانی، ج:۲، ص:۱۲۶)
فائدہ:مجموعۂ عالم میں آسمان، زمین، چرند، پرند، چھوٹے، بڑے حیوانات اور جمادات سبھی داخل ہیں، قیامت آئے گی تو کچھ بھی نہ رہے گا۔ سب کا بقا اہلِ ایمان کی وجہ سے ہے اور ایمان کی دولت رحمۃٌ للعالمین سے ملی ہے، اس اعتبار سے آپ کا رحمۃٌ للعالمین ہونا ظاہر ہے۔ (انوار البیان، ج:۶، ص:۱۷۲)
حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ’’أنا رحمۃ مہداۃ برفع قوم وخفض آخرین‘‘ (ابن کثیر، ج:۳، ص:۲۵۱) یعنی ’’میں اللہ کی بھیجی ہوئی رحمت ہوں، تاکہ اللہ کا حکم ماننے والی قوم کو سربلند کردوں اور دوسری قوم جو اللہ کا حکم ماننے والی نہیں ہے ان کو پست کردوں۔‘‘ اس سے معلوم ہوا کہ کفر وشرک کو مٹانے کے لیے کفار کو پست کرنا اور ان کے مقابلہ میں جہاد کرنا بھی عین رحمت ہے، جس کے ذریعے سرکشوں کو ہوش آکر ایمان اور عمل کا پابند ہوجانے کی اُمید کی جاسکتی ہے۔ (معارف القرآن، ج:۶، ص:۳۳۴)
فائدہ:علامہ آلوسیؒ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عالمین کے ہرفرد کو شامل ہے، خواہ وہ ملائکہ ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں، مؤمن ہوں، کافر ہوں، چنانچہ فرماتے ہیں:
’’والذی اختارہ أنہ ﷺ إنما بعث رحمۃ لکل فرد فرد من العالمین ملائکتہم وإنسہم وجنہم ولافرق بین المؤمن والکافر من الإنس والجن في ذلک۔‘‘ (روح المعانی، ج:۹، ص:۱۵۶)
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت تھے، جیساکہ حسب ذیل روایت سے معلوم ہوتاہے:
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاگیا کہ آپ مشرکین کے لیے بددعا کریں، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: ’’إني لم أبعث لعاناً وإنما بعثت رحمۃً‘‘ یعنی ’’میں لعنت کرنے والا بناکر نہیں بھیجا گیا، بلکہ رحمت بناکر بھیجا گیا ہوں۔‘‘ (روح المعانی، ج:۹، ص:۱۰۶)
حضرت ابوامامۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ نے مجھے عالمین کے لیے رحمت بناکر اور متقیوں کے لیے ہدایت بناکر بھیجا ہے: ’’إن اللہ بعثني رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین۔‘‘ (الدرالمنثور، ج:۴، ص:۶۱۴)
حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ: میں بھی ایک بشر ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، مجھے بھی ایسے غصہ آتاہے جیسے تم کو آتاہے، البتہ چونکہ میں رحمۃٌ للعالمین ہوں، تو میری دعا ہے کہ خدا میرے الفاظ کو بھی ان لوگوں کے لیے موجبِ رحمت بنادے۔ (ابن کثیر، ج:۳، ص:۲۰۲)
شیخ ابوبکر بن طاہرؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زینتِ رحمت سے مزین فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رحمت ہے اور جس کو دیکھا اس پر رحمت ہے اور آپ کا خوش ہونا بلکہ ناراض ہونا اور آپ کا نزدیک ہونا، بلکہ دور کردینا اور تمام شمائل وصفات آپ کی رحمت ہیں، پس جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے کچھ پہنچا، وہ دونوں جہاں میں ہرناپسند سے نجات پانے والا ہے اور اپنی مراد کو پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی رحمت ہے اور آپ کا وفات فرمانا بھی رحمت ہے، جیساکہ حدیث پاک میں ہے کہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میری زندگی تمہارے واسطے رحمت ہے اور میری موت تمہارے لیے رحمت ہے۔ (الشفاء، ج:۱، ص:۱۰۱)
فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت کے لیے باعثِ رحمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں شریعتِ مطہرہ کے احکام ومسائل بیان فرمائے تھے، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مطہر‘ عذاب سے مانع اور آپ کی موت باعثِ رحمت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر اور جمعرات کے دن مجھے اپنی امت کے اعمال دکھائے جاتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں اللہ کی حمد کرتاہوں اور اگر برے اعمال ہوتے ہیں تو امت کے ان افراد کے لیے استغفار کرتاہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: میں اپنی وفات کے بعد اپنی قبر میں صور پھونکے جانے تک اپنی امت کے لیے ’’أمتي أمتي‘‘ کہہ کر اللہ سے بلندیِ درجات اور بخشش کی دعا کرتارہوںگا: ’’إذا مت لا أزال أنادي في قبري أمتي أمتي حتی ینفخ في الصور۔‘‘ (نسیم الریاض، ج:۱، ص:۱۰۲)
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ مؤمنوں کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا وآخرت میں رحمت تھے اور غیر مؤمنوں کے لیے بھی آپ دنیا میں رحمت تھے کہ وہ زمین میں دھنسائے جانے سے اور آسمان سے پتھر برسائے جانے سے بچ گئے، جیسے اگلی امتوں کے منکروں پر یہ عذاب آئے۔ (ابن کثیر، ج:۳، ص:۲۰۱)
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایاکہ: اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جب کسی اُمت پر کرم فرماتے ہیں تو اس کے نبی کو اُمت کی ہلاکت سے پہلے ہی اُٹھالیتے ہیں، پھر وہ نبی اپنی امت کے لیے پیش رو ہوتا ہے: ’’فجعلہ لہا فرطا وسلفا‘‘ اور جب کسی امت کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس نبی کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کردیتے ہیں اور نبی ان کے عذاب کا مشاہدہ کرتاہے اور اپنی امت کی ہلاکت سے آنکھیں ٹھنڈی کرتاہے کہ انہوں نے اس کی تکذیب کی ہوتی ہے اور اس کے حکم کی نافرمانی کی ہوتی ہے۔ (مسلم، ج:۲، ص:۲۴۹)
فائدہ:’’فرط‘‘ آنے والے قافلے کے لیے پہلے سے انتظامات کرنے والے شخص کو ’’فرط‘‘ کہتے ہیں، یعنی ’’پیش خیمہ۔‘‘
ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے فرمایا : اے جبرئیل! کیا آپ کو میری رحمت سے کچھ فائدہ حاصل ہواہے؟ اس پر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے فرمایا : جی ہاں! وہ اس طرح کہ مجھے اپنے سوء خاتمہ کا خوف لاحق تھا، لیکن جب آپ پر قرآن پاک کی آیت ’’اِنَّہٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ کَرِیْمٍ ذِیْ قُوَّۃٍ عِنْدَ ذِی الْعَرْشِ مَکِیْنٍ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِیْنٍ‘‘ (التکویر:۱۹تا ۲۱) نازل فرماکر اللہ تعالیٰ نے میری تعریف فرمائی تو مجھ سے یہ خوف ختم ہوگیا: ’’والمراد: فصرت ببرکۃ القرآن الذي نزل علیک لثناء اللہ عز وجل علیَّ بقولہ: ’’ذِیْ قُوَّۃٍ عِنْدَ .. الخ‘‘۔‘‘ (الشفاء، ج:۱، ص:۱۰۵)
علامہ ابن القیمؒ نے ’’مفتاح السعادۃ‘‘ میں لکھا ہے کہ:
’’ اللہ پاک انبیاء علیہم السلام کو اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بناکر نہ بھیجتے تو پورے عالم میں یقینی طور پر علم نافع نہ ہوتا، اور نہ کہیںعمل صالح نظر آتا، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی اچھائی نظر آتی اورنہ ہی کسی مملکت میں کوئی مضبوطی دکھائی دیتی، اور لوگ، جانور، درندے، پھاڑنے والے اور باؤلے کتے کی طرح ہوکر ایک دوسرے پر حملے کرکے جان لینے والے ہوتے۔ پورے عالم میں کہیں بھی کسی صورت میں خیر کی چنگاری نظر آتی ہے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آثارِ تعلیمات کے نتیجے میں سے ہے اور ہرقسم کا شر جو عالم میں واقع ہواہے یا ہوگا وہ آثارِ نبوت، تعلیماتِ نبوت کے پردۂ خفا میں چلے جانے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ عالم بمنزلہ جسم کے ہے اور اس کی روح نبوتِ محمدی( صلی اللہ علیہ وسلم ) ہے اور کوئی بھی جسم بغیر روح کے قائم نہیں ہوسکتا، اس لیے جب نبوت کا سورج عالم میں گرہن ہوگا اور نبوت کے آثار وتعلیمات دنیا میں باقی نہ رہیںگے تو آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جھڑ جائیںگے، سورج لپیٹ لیا جائے گا، اس لیے دنیا کا قیام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت کے آثار وتعلیمات کے بقا میں ہے۔‘‘ (روح المعانی، ج:۹، ص:۱۰۵)