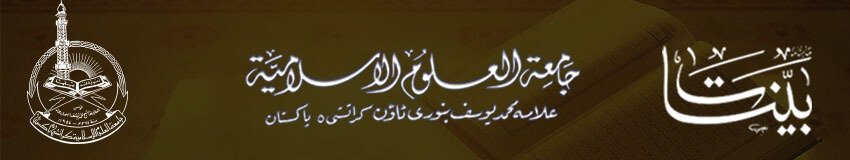
علمِ حدیث اور علمِ رجال سے ادنیٰ سے تعلق کے حامل پر علامہ ذہبی ؒ کا مقام ومرتبہ، اور علمِ رجال میں آپؒ کی مہارتِ تامہ مخفی نہیں ہے، آپ ؒکی علمِ حدیث ودیگر علمی موضوعات کی تصانیف مشہور و معروف ہیں، اور آپؒ کی ہر ایک کتاب کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
آپؒ کی ان تالیفات میں سے ایک اہم تالیفِ لطیف اور فنِ أسماء الرجال سے متعلق ’’تذکرۃ الحفاظ‘‘ کے اسلوب ومنہج اور اس کے خصائص کا بیان آنے والی سطور میں قلم وقرطاس کے سپرد کیا جارہا ہے۔
علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ (م:۸۵۲ھ) لکھتے ہیں:
’’آپ کا نام ’’محمد بن احمد بن عثمان بن قایماز بن عبد اللہ‘‘، کنیت: ’’ابو عبد اللہ‘‘، لقب’’ الذہبی ‘‘ ہے۔ ولادت ۳؍ربیع الاول ۶۷۳ھ میں ہوئی، پیدائش اور وفات دمشق میں ہوئی، علم کے لیے مختلف شہروں کا سفر کیا، وفات سے چند سال قبل آنکھوں کی بینائی سے محروم ہوئے، سیکڑوں تصانیف آپ کے قلم سے منصہ شہود پر آئی ہیں۔‘‘ (۱)
اس حوالہ سے دونوں طرح کے اقوال ہیں:
۱- ابنِ ذہبی ہے؛ اس لیے کہ ’’ذہبی ‘‘ آپ کے والد کا لقب تھا؛ کیونکہ وہ پِسے ہوئے سونے کے پیشہ سے وابستہ تھے، تو ان کا لقب ’’ذہبی‘‘ (یعنی سونے کی صنعت سے منسلک آدمی) پڑگیا، اور والد کی طرف نسبت کی وجہ سےآپؒ کو ’’ابنِ ذہبی‘‘ کہا جاتا ہے، چنانچہ آپ کی اپنی کچھ کتابوں پر لکھی ہوئی تحریروں میں یہی رقم ہے۔
۲- ابتدا میں آپ بھی والد کے ساتھ اسی سلسلۂ تجارت سے منسلک تھے، بعد میں اُسے ترک کردیا، اسی وجہ سے آپ کو بھی اس لقب کے ساتھ ملقب کیا گیا، اور آپ کے معاصرین و تلامذہ مثلاً علامہ تاج الدین سبکیؒ (م:۷۷۱ھ) اور عماد الدین ابن کثیر دمشقیؒ (م:۷۷۴ ھ) نے ’’ابن ذہبی‘‘ تحریر کیا ہے۔(۲)
علامہ شوکانیؒ (م:۱۲۵۰ھ) آپؒ کے علمی اسفار کے بارے میں رقم طراز ہیں:
’’ علامہ ذہبیؒ نے علمی سفر کا آغاز (۶۹۰ھ) کے بعد کیا، اولاً علامہ ابن عساکر دمشقی ؒ سے خوب استفادہ کیا، پھر قاہرہ کی طرف کوچ کیا، اور وہاں کے مشائخ (خصوصاً) علامہ دمیاطی، ابن الصواف کی خدمت میں رہ کر اپنی علمی پیاس بجھائی، نیز تقریباً تیس (۳۰) شہروں کی طرف سفر کرنے کے بعد فنِ حدیث میں خوب مہارت حاصل کی، اور ڈھیر ساری کتابیں صرف اس فن میں تالیف فرمائیں۔‘‘(۳)
’’آپؒ کےمعروف اساتذہ میں علمِ رجال کےماہر علامہ مِزیؒ (م:۷۴۲ھ)، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ (۷۲۷ھ)، اورابو محمدالقاسم بن محمد البرذلی ؒ (م:۷۳۹ھ) جیسی نابغۂ روزگار شخصیات شامل ہیں۔‘‘(۴)
حافظ ذہبی ؒ کو اپنے شیوخ میں سب سے زیادہ قلبی لگاؤ اور محبت ’’علامہ ابن تیمیہؒ ‘‘ سے تھی، اور انہی سے سب سے زیادہ متاثر دکھائی دیے، جبکہ حافظ نے آپؒکو ’’الشیخ، الإمام، العلامۃ، الناقد، الفقيہ، المجتہد، المفسر، البارع، شیخ الإسلام، علم الزہاد، نادرۃ العصر‘‘ جیسے بلند القابات سے نوازا، حتیٰ کہ غایتِ عقیدت میں یہاں تک کہہ دیا:
’’وھو أکبر من أن ينبِّہ مثلي علی نعوتہٖ، فلو حُلِّفتُ بین الرکن والمقام لحلفت أني مارأیتُ بعینيَّ مثلہٗ، ولا واللہ مارأیٰ مثلَ نفسہٖ۔‘‘(۵)
’’آپ کا مقام اس سے بلند ہے کہ مجھ جیسا شخص ان کے اوصاف بیان کرے، اگر میں مقامِ ابراہیم اور رکنِ یمانی کے درمیان قسم اٹھاؤں تو کہہ سکتا ہوں کہ بخدا میں نے اپنی آنکھوں سےآپ جیسی شخصیت نہیں دیکھی اورقسم اللہ کی نہ آپ ؒنے علم میں اپنا مثل دیکھا۔‘‘
آپ کو انتقال سے چار سال پہلے آشوبِ چشم کا مرض لاحق ہوگیا تھا، جس کی وجہ سے بینائی سے محروم ہوئے، اور وفات تک اسی حالت میں رہے، اس دوران اگر کوئی علاج کا مشورہ دیتا، اس پرغصہ کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے:
’’إنما أنا أعرف بنفسي، لأنني ما زال بصري ینقص قلیلا قلیلا إلٰی أن تکامل عدمہٗ۔‘‘
’’مجھے اپنی حالت کا زیادہ علم ہے، میری بصارت آہستہ آہستہ جاتی رہی، حتیٰ کہ اب مکمل ختم ہوگئی۔‘‘
بالآخر شب دو شنبہ، ۳؍ ذی القعدہ، سن۷۴۸ھ کو علم وعمل کا یہ ماہتاب و آفتاب غروب ہوگیا، رحمہ اللہُ رحمۃً واسعۃً۔(۶)
اگرچہ آپ کو تقریباً تمام علوم وفنون پر کامل دسترس تھی، لیکن تصنیف کے لیے آپ نے علمِ حدیث کے میدان کا چناؤ کیا، اور فنِ جرح وتعدیل، مصطلحاتِ حدیث، اسماء الرجال، عقائد، علمِ فقہ، تراجم، اورفنِ تاریخ میں عاشقانِ علم کے رُوبرُو بیش بہا تصنیفات پیش کیں۔ ذیل میں آپ کی کتبِ مؤلفہ میں سے چند ناموں کا ذکر کیا جاتا ہے: ’’سیر أعلام النبلاء (۲۵ جلدیں)، تاریخ الإسلام ووفیات مشاہير الأعلام، تذکرۃ الحفاظ، الموقظۃ في علم مصطلح الحدیث، العذب السلسل في الحدیث المسلسل، میزان الاعتدال في نقد الرجال، العبر في خبر من غبر‘‘ ائمہ اربعہ متبوعینؒ نیز ائمہ احناف میں سے صاحبینؒ کے تراجم پر مشتمل تصانیف سمیت سینکڑوں کتابیں شامل ہیں، جن کی تعداد تقریباً ۲۱۵ ہے۔
تالیفات وتصنیفات کے ناموں کی مکمل فہرست موضوعات کی ترتیب پر شیخ بشار عواد معروف حفظہ اللہ نے ’’مقدمۃ سير أعلام النبلاء‘‘ اور شیخ ابو ہاجر محمد السعید نے ’’مقدمۃ العبر في خبرمن غبر‘‘ میں جمع کردی ہے۔ نیز مطبوع اور غیر مطبوع کی وضاحت بھی شامل کی ہے۔
آپ نے جن کتابوں کی تالیف میں اہلِ علم سے اپنا لوہا منوایا، ان میں سے ’’ تذکرۃ الحفاظ‘‘ جیسی کتاب کی تالیف کا سہرا بھی آپ کے سر ہے، جسے آپ کے بلند علمی مقام اور اس میں تحقیقی مزاج کے باعث اہلِ علم کے حلقوں میں خوب پذیرائی ملی۔
اربابِ قلم اورعلمی حلقوں میں اس کتاب کی شہرت ’’تذکرۃ الحفاظ‘‘ اور ’’طبقات الحفاظ‘‘ دونوں ناموں سے ہے۔ علامہ سیوطی ؒنے’’طبقات الحفاظ‘‘ میں، اور علامہ کتانیؒ (۱۳۴۵ھ) نے ’’الرسالۃ المستطرفۃ‘‘ میں کتبِ طبقات کی بحث میں اس کا نام ’’طبقات الحفاظ‘‘ ذکر کیا۔
اور شیخ بشار عوادحفظہ اللہ نے ’’سیر أعلام النبلاء‘‘ کے مقدمہ میں، نیز ’’الکاشف في معرفۃ من لہ روايۃ في الکتب الستۃ‘‘ کے مقدمہ میں فہرستِ تصانیف کے بیان میں ’’لجنۃ العلماء‘‘ نے اسے ’’تذکرۃ الحفاظ‘‘ کے نام سے موسوم کیا۔
کتاب کا ایک نسخہ وہ ہے جسے ہندوستان میں ’’دائرۃ المعارف العثمانيۃ‘‘( دکن) نے ۱۳۳۳ھ میں طبع کیا، اس کا ایک مصور ’’حرمِ مکی‘‘ میں موجود اصل نسخہ سے تصحیح شدہ ایڈیشن بیروت میں ’’دار إحیاء التراث العربي‘‘ سے ۱۳۷۶ھ میں طبع ہے، اورچاروں جلدوں کو دو جلدوں میں ضم کرکے شائع کیاگیا۔ علاوہ ازیں ’’دار الکتب العلمیۃ‘‘ بیروت سے بھی اس کا ایڈیشن ہے، جس کے سرورق پر اس بات کی وضاحت شامل کی گئی ہے کہ ’’اس نسخہ کی تصحیح حرمِ مکی میں موجود اصل نسخہ سے کی گئی ہے۔‘‘ نیزایک ایڈیشن ’’دار الکتب العلمیۃ ‘‘ کی طرف سے شیخ زکریا عمیرات کے حواشی کے ساتھ پانچ جلدوں میں ہے، اوراس کی پہلی طباعت کا سن ۱۴۱۹ھ ہے، نیز اس میں اس پر تینوں ’’ذیول‘‘ بھی شامل کیے گئے ہیں، البتہ اس ایڈیشن میں کافی اغلاط ہیں۔ ’’دار الکتب العلمیۃ‘‘ ہی کے ’’دائرۃ المعارف‘‘ سے مصور ایک ایڈیشن پر شیخ عبد الرحمٰن بن یحییٰ المعلمی کی تحقیق بھی شامل ہے۔
اس کتاب پر تین حضرات کے ذیول مطبوعہ شکل میں ہیں :
۱-سب سے پہلے آپؒ کے تلمیذ حافظ ابو المحاسن الحسینی الدمشقی ؒ (۷۶۵ھ) نے ’’ذیل تذکرۃ الحفاظ‘‘ کے نام سے اس کا ذیل پیش کیاہے۔
۲-دوسرا ذیل ’’لحظ الألحاظ بذیل طبقات الحفاظ‘‘ کے نام سے محمد بن فہد مکیؒ (م:۸۷۱ھ) نے لکھاہے۔
۳-نیز’’علامہ سیوطی ؒ‘‘نے بھی ’’طبقات الحفاظ‘‘ کے نام سے اس پر ذیل اورتلخیص پیش کی، البتہ علامہ سیوطیؒ نے تین طبقات میں مزیدحفاظ کا تذکرہ بھی شامل کیا، چنانچہ اس میں طبقات کی تعداد۲۴ ہے۔
علامہ سیوطیؒ کی یہ کتاب ’’وِستِنفلدغوننجی‘‘(مستشرق) کی تحقیق سے مزین ہوکر ۱۲۷۷ھ میں طبع ہوئی ہے، نیز بیروت سے بھی مطبوع ہے۔
آخر الذکر دونوں ذیول پر ’’شیخ محمود سعید ممدوح‘‘ نے ’’تزیین الألفاظ بتتمیم ذیول تذکرۃ الحفاظ‘‘ کے نام سے تتمہ پیش کیا، اور خطبۂ کتاب کے بعد اس مقصد کی صراحت مذکور ہے، البتہ تراجم کے آغاز سے پہلے کچھ فصول قائم کرکے مفید مباحث شامل کیے ہیں، جو قابلِ مطالعہ ہیں۔
یہ تینوں ’’ذیول‘‘ یکجا مکتبہ’’ ابن تیمیہ‘‘ سے بھی طبع شدہ ہیں۔
اسی طرح ان تینوں کو ’’علامہ کوثریؒ‘‘ (۱۳۷۷ھ) نے بھی اپنی مفید تعلیقات کے ساتھ جمع کرکے ایک جلد میں شائع کرایا ہے۔
’’علامہ کوثریؒ‘‘ کی ان تعلیقات اورطبع کردہ ’’ذیول‘‘ پر شیخ احمد رافع الحسینی نے ’’التنبيہ والإیقاظ لما في ذیول تذکرۃ الحفاظ‘‘ کے نام سے ۱۶۶ صفحات پر ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اس نسخہ، اور اس پر لکھی گئی تعلیقات کی مزید توضیح اوراصلاح کی، اور یہ ’’دار إحیاء التراث العربي‘‘ سے ان تینوں ’’ذیول‘‘ کے ساتھ آخر میں شامل اور ملحق ہے، جبکہ اس کے پہلے صفحہ کے حاشیہ میں علامہ کوثریؒ نے مصنفؒ کے لیے تشکر آمیز کلمات بھی نقل کیے ہیں۔ مصنف کا اُسلوب یہ ہے کہ ہر ایک ذیل کو عنوان کی شکل دے کر سطر نمبر اور صفحہ نمبر رقم کرنے کے بعد اپنی تحقیق پیش کرتے ہیں۔
آپ خود مقدمہ میں حمد وصلاۃ کے بعد کتاب کے لکھنے کا بنیادی مقصد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
’’ہٰذہٖ تذکرۃ بأسماء معدّلي حملۃ العلم النبويّ ومن یرجع إلی اجتہادھم في التوثیق والتضعیف، والتصحیح والتزییف۔‘‘
ترجمہ: ’’یہ مجموعہ حاملینِ علمِ نبوی-صلی اللہ علیہ وسلم- کی عدالت بیان کرنے والوں کے ناموں پرمشتمل ہے، جن کی طرف راوی کی توثیق وتضعیف، اورحدیث کے کھرے اور کھوٹے پن میں رجوع کیا جاتا ہو۔ ‘‘
علامہ محمدعبد الرشید نعمانیؒ (م:۱۴۲۰ھ) حافظ ذہبیؒ کے اس جملہ کو نقل کرنے کے بعد رقم طراز ہیں:
’’ حافظ موصوف نے تمام کتاب میں اس اصول کو ملحوظ رکھا ہے اور کسی ایسے شخص کا ترجمہ نہیں لکھا، جوحدیث میں حافظ شمار نہ کیا جاتا ہو (اگرچہ دوسرے علوم میں امام تسلیم کیے جاتے ہوں، مثلاً :ابو محمد عبد اللہ بن قتیبہ)، اسی طرح ان لوگوں کا تذکرہ بھی اس کتاب میں نہیں لکھا، جواگرچہ حدیث میں حافظ تھے، مگر(اکثر- از ناقل)محدثین کے نزدیک ’’متروک الروایۃ‘‘ خیال کیے جاتے تھے، مثلاً: ہشام بن محمد کلبی اور علامہ واقدی۔‘‘(۷)
حافظ ذہبیؒ نے اس کتاب میں تراجمِ محدثینِ حفاظ کوطبقات کی صورت میں پیش کیا۔
لفظ طبقات’’طبقۃ‘‘ کی جمع ہے، اور اس کا معنی لغت میں ہے:
’’ نسل در نسل، ایسے لوگ جو عمر اور زمانہ، یا مرتبہ اور حالت میں ایک دوسرے کے مشابہ ہوں۔‘‘ (۸)
علامہ سیوطیؒ (م:۹۱۱ ھ) ’’تدریب الراوي‘‘ میں لکھتےہیں:
’’الطبقۃ في اللغۃ: القوم المتشابہون، و في الاصطلاح : قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، بأن یکون شیوخ ہٰذا ہم شیوخ الآخر أو یقاربوا شیوخہٗ۔‘‘(۹)
’’طبقہ، لغت میں ’’ایک جیسے لوگوں‘‘ کو کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں اس کا اطلاق ایسی قوم پر ہوتا ہے جو عمر اور سند یا صرف سند میں ایک دوسرے کے متقارب ہوں کہ ایک کے شیوخ دوسرے کے شیوخ ہوں یا اس کےشیوخ کے قریب قریب ہوں۔‘‘
کیا طبقہ کے لیے کوئی تحدید اور تعیین ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دو طبقات کے مابین حدِفاصل قائم کرنا مشکل امر ہے، کیونکہ طبقات پر لکھنے والوں نےکسی مخصوص سن کا لحاظ نہیں رکھا۔ (مزید تفصیل کے لیے اصل مرجع ملاحظہ ہو)۔ (۱۰)
’’علامہ سیوطیؒ ‘‘( م:۹۱۱ ھ) نے ’’تدریب الراوي‘‘ شرح ’’ تقریب النواوي‘‘ (۱۱)میں اس لفظ کے ضمن میں نہایت بسط سے کام لیا، اور مختلف اقوال نقل کیے ہیں، ان سب کا لبِ لباب علامہ ظفر احمد عثمانیؒ (۱۳۹۶ھ) کی ’’أحادیث الأحکام‘‘ پر بلند پایہ کتاب ’’إعلاء السنن‘‘ کے مقدمہ میں موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے:
’’محدّث اسے کہتے ہیں جو اِثباتِ حدیث کے تمام طرق کا علم رکھے، اور اس کے رواۃ کی جرح وتعدیل کی معرفت حاصل کرے، نیزصرف سماع پر انحصار نہ کرتا ہو۔ اگر وہ مزید ترقی کرے، حتیٰ کہ اپنے شیوخ، اور طبقہ وار اپنے مشائخ کے بھی شیوخ، یہاں تک کہ اتنےرواۃِحدیث کا اسے علم ہوجائے جو تعداد میں دیگر نامعلوم راویانِ حدیث سے زیادہ ہوں، تو اسے ’’حافظ‘‘ کہا جائے گا۔‘‘(۱۲)
اسی طرح شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ؒنے اس مقام پر حاشیہ قلمبند کیا، ملاحظہ کیجیے:
’’صحیح بات یہ ہے کہ اس کا دارومدار ہر زمانہ کے اعتبار سے اس کے اہل پر چھوڑدیا جائے، پس ’’حافظ‘‘ وہ ہے جو کسی حدیث کو سن کر یہ فیصلہ کرسکتا ہو کہ یہ حدیث صحاح کی کتب میں سے ہے یا نہیں اور اسے ہزار یا اس سے زیادہ احادیث بالمعنی حفظ ہوں۔‘‘
آگے ’’شیخ عبد الفتاحؒ‘‘ اسی قول پر اپنے شیخ’’ علامہ محمد زاہد الکوثریؒ ‘‘ (۱۳۷۷ھ)کے حوالہ سے فرماتے ہیں:
’’شیخ ظفر (احمد) عثمانی ؒ کے اس قول کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ’’ ایک دفعہ میں نے اپنے شیخ علامہ کوثریؒ سے ’’حافظ، حجۃ ‘‘ اور ’’حاکم‘‘ کی تعریفات کے مآخذ اور مستندات کا پوچھا، تو آپؒ نے جواب میں فرمایا: ’’یہ بعدوالوں کی اصطلاح ہے، جو سلف سے منقول نہیں۔‘‘
بلکہ علامہ ذہبیؒ نے اپنی تالیف ’’تذکرۃ الحفاظ ‘‘ میں بعض ان صحابہؓ کا بھی ذکر کیا، جو ان تعریفات کی رو سے ان احادیث کا دسواں حصہ بھی روایت نہیں کرتے، جتنی احادیث کی تعداد‘حافظ، حجۃ، اور حاکم کی تعریفات میں بیان کی جاتی ہے۔‘‘ (ایضاً، ازحاشیہ)
’’السراج المنیر في ألقاب المحدثین‘‘ میں لفظ ’’حافظ‘‘ کے حوالہ سے بہترین بحث لکھی گئی ہے، چنانچہ اس کی اصطلاحی تعریف کے تحت لکھا ہے:
’’سلف کے نزدیک’’ محدّث‘‘ اور ’’حافظ‘‘ کا ایک معنی ہے، نیزان حضرات نے ہردو کو دوسرے کی جگہ استعمال کیا، نیز ایک کی تعریف کا اطلاق دوسرے پر کرتے ہیں۔ البتہ بعد میں آنے والوں نے اس میں فرق کیا اور ’’حافظ‘‘ کا مرتبہ ’’محدث‘‘سے مافوق اور’’ حجۃ‘‘ سے نیچے رکھا، البتہ اس پر اتفاق کے باوجود ’’حافظ‘‘ کی تعریف میں مختلف تعبیرات استعمال کی گئی ہیں۔‘‘ (۱۳)
’’حافظ ذہبیؒ نے کتاب کے اکیس طبقات میں کل۱۱۷۶؍حفاظ کے احوال پیش کیے ہیں۔‘‘
ہرگز نہیں، بلکہ خود آپؒ نے تراجم کے اختتام کے بعد صراحت کے ساتھ لکھا ہے: ’’یہاں تک ہماری کتاب ’’تذکرۃ الحفاظ‘‘ کا اختتام ہوگیا، اور ممکن ہے کہ غفلت اور نسیان کی وجہ سے بہت سے ان لوگوں کا ذکرچھوٹ گیاہے، جو ان حفاظ کےعلم و حفظ کے مرتبہ میں ان کے مساوی ہیں۔‘‘
حافظ ذہبی ؒ نے مندرجہ ذیل وجوہ سے حفاظ کی ترتیب اختیار کی اور ان کے مناقب اور اوصاف وکمالات ذکر کیے ہیں:
۱- کل ۲۱؍طبقات کے ہرہر طبقہ میں ذکر کردہ حفاظِ حدیث کی تعدادبالترتیب درج ذیل ہے:
۷، ۱۵، ۱۲، ۲۶، ۲۵، ۱۸، ۴۶، ۳۱، ۷۴، ۷۹، ۷۷، ۱۱۷، ۱۰۶، ۱۳۰، ۱۰۶، ۸۱، ۷۸، ۵۸، ۳۰، ۴۲، ۲۳۔
نوٹ: یہ تعداد اور ترتیب ِطبقات، تذکرۃ الحفاظ مطبوعہ’’ دارإحیاء التراث العربي بیروت‘‘ سے ماخوذ ہے، جو دو جلدوں میں ہیں، اور ہر جلد دو حصوں پر ہے۔
۲- سب سے پہلے صحابہ کرامؓ کا طبقہ رکھا، جس میں۲۳ صحابہ کرام -رضی اللہ عنہم- کے تراجم پر روشنی ڈالی، ان میں خلفاء اربعہؓ کو مقدم رکھا، اس کے بعد حضرت ابن مسعودؓ (۳۲ھ) و دیگر حفاظ صحابہؓ۔ علاوہ ازیں صحابہ کرامؓ کے طبقہ میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسماء کا ذکر بھی شامل کردیا، جن کی حدیث کی صحیح کتب میں مرویات ہیں، (اگرچہ ان کا حفاظ میں شمار نہ ہو) بلکہ انہی میں سے راویات کے ناموں کا بیان بھی ملحق ہے۔
۳-سب سے آخر میں اپنے محبوب استاد علامہ مزی ؒ کا ترجمہ درج کیا، اور ان کے لیے عظیم القابات ذکر کیے، ان کا علمی مرتبہ اور مقام قارئین کی خدمت میں پیش کیا۔
۴- ان سے قبل اپنے دوسرے محبوب استاذ علامہ ابن تیمیہؒ کا ذکرِ خیر کرتے ہوئے ان کے کمالاتِ علمیہ کو ذکر کیا، البتہ عالی القابات سے نوازنے کے بعد آپؒ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا، چنانچہ ملاحظہ ہوں:
’’علامہ ابن تیمیہؒ کچھ فتاویٰ اور آراء میں دیگر جمہور اہلِ علم سے متفق نہیں، البتہ ایسی باتوں کو آپ کے علم کی گہرائی نے ڈھانپ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ سے درگزر فرمائیں، میں نے آپ جیسی شخصیت نہیں دیکھی، اور ہر ایک پر ان کے اقوال میں مواخذہ کیا جاسکتا ہے، تو آپ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔‘‘
۵- ہر طبقہ کا آغاز کرتے ہوئے اس میں ذکر کردہ حفاظ کی تعداد ذکر کرنے کا اہتمام کرنا۔
۶- کتاب میں صاحبِ ترجمہ ’’حفاظ‘‘ کی مرویات کے لیے متعلقہ کتاب کے حوالہ کے لیے درج ذیل رموز مقرر ہیں:
صحیح بخاری (خ)، صحیح مسلم(م)، سنن ابی داود(د)، سنن نسائی(س)، سنن ترمذی(ت)، سنن ابن ماجہ (ق) سنن اربعہ (۴)، اُمہاتِ کتبِ ستہ(ع)۔
۷- حافظ کے تذکرہ میں ان کا نام، والد کا نام، کنیت کا ذکر، نیز نسب نامہ اور علمی القابات کا ذکر کرتے ہیں۔
۸- ان کی تاریخ، سنِ ولادت او روفات کا ذکر کرتے ہیں۔
۹- اس ضمن میں مشہور ومعروف اساتذہ اور تلامذہ کا ذکر بھی کرتے ہیں ۔
۱۰-اگر کسی حافظ کی کوئی روایت کتبِ ستہ میں ہو، تو اس کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، لیکن اس کےلیے ایک علامت مخصوص ہے، (جس کاسابق میں ذکر ہوچکا)، جس سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔
۱۱- اگران کے بارے میں واقعات یا مدحیہ کلمات کسی امام یا مشہور اہلِ علم سے منقول ہوں، تو اسے بھی زیرِقرطاس لاتے ہیں۔
۱۲- اس کے علاوہ اگر ان کی کوئی روایت امام ذہبیؒ تک متصل ہو، تو اس کو سند کے ساتھ بیان کرنے کا اہتمام کرتے ہیں۔
۱۳- اگر کسی مشہور شخصیت کا اس طبقہ میں انتقال ہوا ہو تو اسے بھی سپردِ قلم کرتے ہیں۔
۱۴- صاحبِ ترجمہ کا فقہی مسلک بھی واضح کرتے ہیں۔
۱۵- آپؒ بہت سے حفاظ کے تذکرہ کےذیل میں ان کے خوفِ خداوندی اور خشیت کے قصص نقل کرتے ہوئے پڑھنے والے کو گویا یہ نصیحت کرتے ہیں کہ: ’’اپنے علم کی حفاظت کے لیے تقویٰ کو ڈھال بنادے، اور فخر وعجب میں مبتلا نہ ہو، بلکہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے۔‘‘
۱۶- حافظ ذہبیؒ نے (باوجود شافعی المسلک ہونے کے) ا س کتاب کے ’’طبقۂ خامسہ‘‘ میں ائمہ اربعہ متبوعین میں سے امام ابو حنیفہؒ (م:۱۵۰ھ) کا تذکرہ بھی پیش کیا، اور آپؒ کو حدیث کے باب میں ’’حافظ‘‘ کا لقب عنایت کیا۔ یہ ان لوگوں کے خلاف واضح دلیل ہے، جو ضعیف اور غیر مستند اقوال کا سہارا لے کر آپ کو حدیث کے باب میں ’’تہی دامنی‘‘ کا لقب دیتے ہیں، اور مشہور ائمہ علم اور اصحابِ حدیث کو بطور استشہاد پیش کرتے ہیں، لیکن حقیقت تک پہنچنے کی سعی تک نہیں کرتے، حتیٰ کہ بسااوقات امام اعظمؒ کی بےادبی، توہین اور تنقیص تک پہنچ جاتے ہیں، أعاذنا اللہ من ذٰلک۔
۱۷- حضور -صلی اللہ علیہ وسلم- اور آپ -علیہ السلام- کی احادیث کا شوق اور اس کی رغبت دلانے کے لیے ان حفاظ کے اس سے متعلق واقعات بھی بیان کرتے ہیں۔
۱۸- ترجمہ کے ذیل میں صاحبِ ترجمہ کے ’’علمی اسفار‘‘ کا ذکر کرتے ہیں ۔(۱۴)
۱۹- ان حفاظ کی قلمی خدمات سےبھی تعرض کرتے ہیں۔
۲۰- حافظ ذہبیؒ نے کچھ طبقات کے آخر میں یہ اُسلوب بھی اختیار کیا کہ اسی طبقہ کے دیگر راویانِ حدیث، مشہور اہلِ علم یا حدیث سے تعلق رکھنے والوں کے اسماء، یا کسی فتنہ کا ظہور ہوا ہو تو اس کا ان کے عقائدِ فاسدہ کے ساتھ بیان کرتےہیں، (۱۵) اور اس طبقہ کے حفاظ کے زمانہ میں کن خلفاء کا زمانہ رہا، نیز ان خلفاء کے ظلم و جور، انصاف وکارہائے نمایاں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور قارئین کو قدماء محدثین کا مرتبہ سامنے لاکر ان کی شان میں ہذیان بکنے سے اجتناب کی تلقین کرتے ہیں، اور انہیں قدوہ بناکر اتباع کی ترغیب دیتے ہیں، نیزفقہاء کی آڑ لے کر محدثین کوبنظرِ حقارت دیکھنے سے احتراز برتنے جیسے عمدہ اُمور کو اُجاگر کرتے ہیں۔
۲۱- علامہ ذہبیؒ نے طبقات کے ختم ہونے کے بعد اپنے شیوخ کا بھی ضمناً تذکرہ شامل کیا، ان شیوخ کی کل تعداد ۳۶ ہے۔
۱- الدرر الکامنۃ لابن حجرؒ : ۳/۳۳۶، دار الجيل، بيروت، ۱۴۱۴ھ
۲-مقدمۃ سیر أعلام النبلاء: ۱/۱۶، للشیخ بشار محمد عواد معروف ؒ، ط:مؤسسۃ الرسالۃ، طبع سادس ۱۴۱۰ھ
۳-البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: ۲/۳۸، حرف الجیم، ط:دار الکتب العلمیۃ، طبع أول ۱۴۱۸ھ
۴- مقدمۃ سیر أعلام النبلاء: ۱/۳۵، للشیخ بشار محمد عواد معروف ؒ، ط:مؤسسۃ الرسالۃ، طبع سادس ۱۴۱۰ھ
۵- الرد الوافر علی من زعم بأن من سمی ابن تيميۃ شیخ الإسلام کافرا، ابن ناصر الدین الدمشقي، (م: ۸۴۲ھ)، ص:۷۲، المکتب الإسلامي، طبع ثالث، ۱۴۱۱ھ، زھیر شاوش۔
۶- الوافي بالوفیات، مؤلف:صلاح الدین خلیل بن أیبک الصفدي، ۲/۱۶۵، ترجمۃ محمد بن أحمد بن عثمان الذہبي، طبع ثاني، سن ۱۴۰۱ھ/۱۹۸۱ء نیز ’’الدررالکامنۃ‘‘ لابن حجرؒ ۲/۳۳۸، دار إحياء التراث العربي، بیروت، ترجمۃ: محمد ابن أحمد الذھبي۔
۷- امام ابن ماجہؒ اور علمِ حدیث، ص:۱۴۹، میر محمد کتب خانہ
۸- المعجم الوسیط: ۲/۵۵۱، باب الطاء، ط:دار الدعوۃ
۹- تدريب الراوي: ۲/۳۸۱، م: میر محمد کراچی، طبع دوم، ۱۳۹۲ھ/۱۹۷۲ء۔
۱۰- ’’علم طبقات المحدثین، أہميتہ وفوائدہ، المھندس أسعد سالم تیم، ص:۱۲۴، مکتبۃ الرشد، ریاض، طبع أول ۱۹۹۴ء
۱۱- نوٹ: اس کتاب کا پورا نام ’’التقریب والتیسیر في معرفۃ سنن البشیر والنذیر‘‘ ہے، یہ ابو عمرو ابن الصلاح عثمان بن عبد الرحمٰن (م:۶۴۳ھ) کی علم حدیث کے۶۵ انواع کا احاطہ کرنے والی بے مثال کتاب ’’معرفۃ أنواع علم الحدیث‘‘ کی ’’تلخیص التلخیص‘‘ ہے، مصنف نےاولاً ’’إرشاد طلاب الحقائق‘‘ کے نام سے تلخیص کی، اور پھر ’’التقریب ‘‘کے نام سے اس کی تلخیص فرمائی، یہ دونوں ساتویں صدی کے مشہور شافعی المسلک عالم ابوزکریایحییٰ بن شرف الدین النووی الدمشقی (م:۶۷۶ھ) کے قلم سے منصہ شہود پر آئی ہیں، جبکہ اس کی تفصیلی شرح ’’ تدریب الراوي‘‘ جدید طباعت کے ساتھ حال ہی میں عالمِ عرب کےمشہور عالم و محقق اور نقاد ’’علامہ عبد الفتاح ابوغدہؒ‘‘ (۱۴۱۷ھ) کے علمی جانشین ’’شیخ محمد عوامہ -حفظہ اللہ تعالیٰ- کی مایہ ناز تحقیق وتعلیق (جس میں خصوصاً فقہاءِ محدثین کے اصولیین کو بھی بیان کیا گیا ہے) اور آپ کے اہتمام کے ساتھ پانچ جلدوں میں مکتبہ دار المنہاج سے مطبوع ہے۔
۱۲- مقدمۃ إعلاء السنن ۱۹/۲۸، إدارۃ القرآن والعلوم الإسلامیۃ کراچی، تحقیق شیخ عبد الفتاح أبو غدۃ (۱۴۱۷ھ)
۱۳- السراج المنیر في ألقاب المحدثین، مصنف شیخ سعد فہمی بلال، ص:۱۲۸، دار ابن حزم، طبع أول، ۱۴۱۷ھ/۱۹۹۶ء
۱۴- اسفارِ علمیہ کی علت یہ ہے کہ سلفِ صالحین کے ہاں طلبِ علم کے لیے سفر کرنا، اپنے گھر بار چھوڑ کر دوردراز زرِکثیر خرچ کرکے اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیےجانا مستحسن سمجھا جاتا تھا، بلکہ اس پر مستزاد حافظ خطیب بغدادیؒ (م:۴۶۳ھ) کی علمِ حدیث حاصل کرنے کے لیے اسفار کرنے والے اہلِ علم کے تذکرہ پر مشتمل کتاب ’’الرحلۃ في طلب الحدیث‘‘ مستقل تصنیف ہے، جسے بے حد سراہا گیا ہے۔
۱۵- مثلاً طبقۂ رابعہ کے آخر میں بصرہ میں اُٹھنے والے فرقہ قدریہ اور معتزلہ کا ذکر کیا، ان کے قرآن و حدیث سے متصادم عقائد بھی بیان کیے۔ طبقۂ سادسہ کے آخر میں شیعیت ورافضیت کے طلوع ہونے اور اس کے سبب کو بیان کیا۔