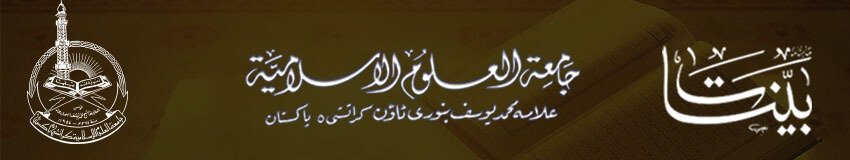
ڈاکٹر عصام عیدو حفظہ اللہ، حلب (شام) کے محقّق عالم اور عالمِ اسلام کے نامور محدّث ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردِ خاص ہیں۔ ’’دمشق یونی ورسٹی‘‘ میں ’’کلیہ شریعہ‘‘ کے ’’شعبہ علومِ قرآن وسنت‘‘ سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اس دوران ڈاکٹر نور الدین عتر کی زیرِ نگرانی لکھا گیا ان کا ڈاکٹریٹ کا مقالہ ’’منہج قبول الأخبار عند المحدثين‘‘ کے نام سے دو جلدوں میں دار المقتبس (بیروت، لبنان) سے شائع ہوچکا ہے۔ بعد ازاں کلیہ شریعہ، دمشق یونی ورسٹی میں ہی لیکچرار رہے، اور اب وینڈر بلٹ یونیورسٹی (امریکہ) میں استاذ ہیں۔ موصوف کی تحقیقی کاوشوں میں سے ’’منہج قبول الأخبار عند المحدثين‘‘ اور ’’نشأۃ علم المصطلح والحدّ الفاصل بین المتقدّمین والمتأخرین‘‘ علومِ حدیث میں معروف ہیں۔ ان کے علاوہ بھی عربی اور انگریزی میں بہت سے تحقیقی مقالات قلم بند کرچکے ہیں۔
۲۰۱۷ء میں عرب دنیا کے معروف علمی، تحقیقی وطباعتی ادارے مرکز نماء للبحوث والدراسات (بیروت، لبنان) سے ’’الدرس الحديثي المعاصر‘‘ کے نام سے متعدد مقالات پر مشتمل ایک کتاب شائع ہوئی تھی، جس میں سعودی عرب، مصر، مغرب، شام اور ہندوستان میں تدریسِ حدیث کے مناہج کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ شام کے تدریسی منہج کے متعلق مقالہ ڈاکٹر عصام عیدو حفظہ اللہ کا تحریر کردہ ہے، اور اس مقالہ کے اصل موضوع سے قبل تمہیدی مباحث موصوف کے مطالعہ وتحقیق کا نچوڑ ہیں اور علومِ حدیث کے طلبہ کے لیے نہایت مفید اور کئی جہتیں واضح کرتے ہیں۔ افادۂ عام کی غرض سے ہلکی پھلکی ترمیم واضافے کے ساتھ مقالہ کے اس حصے کی ترجمانی کی گئی ہے، اُمید ہے علومِ حدیث کے طلبہ کرام اور دیگر اہلِ علم اسے مفید پائیں گے۔ (مترجم)
علمِ مصطلح الحدیث اور تاریخِ علمِ مصطلح کے کئی محقّقین کے مطابق علمِ روایتِ حدیث و علمِ درایتِ حدیث کی تاریخ متعدد تاریخی مراحل اور ادوار میں تقسیم ہے۔ تاریخِ علمِ حدیث کے متعلق اصطلاحی بنیادوں کے تناظر میں شاید دو اُمور کے درمیان امتیاز مناسب ہوگا:
1- دور (مخصوص زمانہ) کی اصطلاح، جو کئی محقّقین کے پیشِ نظر ہے، اور اس کا مقصد مختلف حیثیتوں سے علمِ مصطلح کی تاریخی تقسیم ہے۔
2- مرحلہ کی اصطلاح، جس کا مفہوم وہ منہجی حیثیت ہے، جس کے ذریعے علمِ مصطلح کے مباحث کو اِس علم کی تاریخ کے لحاظ سے حل کرنا مقصود ہوتا ہے۔
محقّق (مقالہ نگار) کی نگاہ میں علمِ مصطلح کی تاریخ تین مراحل میں تقسیم ہے: مرحلہ متقدّمین، مرحلہ متاخّرین، اور مرحلہ معاصرین۔
متقدّمین کا مرحلہ، روایتِ حدیث کے آغاز یعنی عہدِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے شروع ہوتا ہے، اور تیسری صدی ہجری (۱) کی ابتدا میں ختم ہوتا ہے۔ بعض اہلِ علم نے اس مرحلہ کو بھی اس دور میں پیش آمدہ احوال کی تفصیلات کے لحاظ سے تاریخی ادوار میں تقسیم کیا ہے؛ چنانچہ ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرحلے کو تین تاریخی ادوار میں تقسیم کیا ہے:
1- نشوونما کا ابتدائی دور: عہدِ صحابہ رضی اللہ عنہم سے پہلی صدی ہجری کی انتہا تک۔
2- تدریجی تکمیل کا دور: دوسری صدی ہجری کے آغاز سے تیسری صدی کی ابتدا تک۔
3- بکھرے علومِ حدیث کا دورِ تدوین: تیسری صدی ہجری کی ابتدا سے چوتھی صدی کے نصف تک۔ (۲)
ڈاکٹر مصطفی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس (پہلے) مرحلے کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے:
1- دورِ صحابہ رضی اللہ عنہم ۔
2- تابعینؒ سے شروع اور تقریباً چوتھی صدی کے نصف تک۔ (۳)
ڈاکٹر حاتم عارف عونی حفظہ اللہ نے (اس مرحلے کو) پانچ تاریخی ادوار میں تقسیم کیا ہے:
۱- نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے حضرت عثمان بن عفّان رضی اللہ عنہ کی شہادت (سنہ ۳۵ھ) تک۔
۲- شہادتِ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے اکثریت کی رحلت (یعنی تقریباً سنہ ۸۰ھ) تک۔
۳- عہدِ تابعینؒ، جو لگ بھگ ۸۰ھ سے شروع ہوتا ہے، اور اکثر تابعین رحمۃ اللہ علیہم کی وفات (یعنی ۱۴۰ھ) پر ختم ہوتا ہے۔
۴- عہدِ اَتباعِ تابعینؒ، یہ دور سنہ ۱۴۰ھ سے شروع ہوتا اور سنہ ۲۰۰ھ پر ختم ہوتا ہے۔
5- تیسری صدی ہجری۔ (۴)
بلاشبہ تقسیمِ ادوار کا یہ اختلاف، اعتباری ہے؛ کیونکہ اس کی بنیاد گوناگوں حیثیتیں اور اہلِ علم کے نقطہ ہائے نظر کا اختلاف ہے۔ ان میں سے کوئی تقسیم، علمِ مصطلح میں تصنیف کے اعتبار سے ہے، کوئی اس علم کے طریقۂ تعبیر کے پہلو سے ہے، (۵) کوئی روایت وتلقّی کے نقطۂ نظر کی بنیاد پر ہے، (۶) اور کوئی تقسیم‘ احادیث واخبار سے تعامل میں تشدّد اور تساہل کے اعتبار سے ہے۔ (۷)
لیکن مرحلۂ متقدّمین کے ضمن میں ہونے کی بنا پر یہ تمام تاریخی ادوار یکجا ہوجاتے ہیں، کیونکہ یہ مرحلہ ابتدائی تین صدیوں (یعنی عہدِ صحابہ رضی اللہ عنہم ، عہدِ تابعین رحمۃ اللہ علیہم ، عہدِ اتباعِ تابعین رحمۃ اللہ علیہم ، عہدِ متقدّمین ائمہ فقہ وحدیث) پر مشتمل ہے۔ اسی مرحلے میں پہلی صدی ہجری کے آخر میں حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ (سنہ ۱۰۱ھ) کی جانب سے ذخیرۂ سنت کی سرکاری تدوین کا آغاز ہوا۔ (۸)
یہ مرحلہ چند خصوصیات کا حامل ہے:
1- سب سے اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس مرحلے میں نظریۂ اسناد کا ظہور ہوا، جس کی کڑیاں دھیرے دھیرے پھیلتی گئیں؛ کیونکہ روایتِ حدیث کا آغاز مصدرِ خبر (نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہؓ اور تابعینؒ) سے زبانی حصول سے ہوا، پھر مرورِ زمانہ کے ساتھ حلقے بڑھتے گئے، اور سندیں شاخ در شاخ پھیلتی گئیں، اور تیسری صدی ہجری کی انتہا تک سندوں کی کڑیاں پانچ، چھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوگئیں۔
2- سند کے مطالبے سے راویوں کی تحقیق نے جنم لیا، اور عدالت وجرح کا نظریہ وجود میں آیا، پھر اسی سے راویوں اور ان کی مرویات کے درمیان موازنے کا رجحان پیدا ہوا، متابعات کی تلاش ہونے لگی، ایک ہی حدیث کو راویوں کی جماعت سے سننے کی جستجو ہوئی، غریب حدیث کو ناپسند کیا جانے لگا، اور لوگوں کے درمیان متعارف احادیث بیان کرنے کی حرص ہونے لگی۔
3- اسی مرحلے میں علمِ علل کا ظہور ہوا، یہ علم، روایت واسناد کے آغاز کے ساتھ ہی ایک نظریہ کی حیثیت سے وجود میں آیا۔ (۹)
4-عمومی طور پر اس مرحلے میں مختلف جہتوں سے متعلق تصانیف کا مجموعہ سامنے آیا، جو کسی ایک عنوان یا مقصد کے تحت نہیں سمٹ سکتیں، ان میں سے بعض کسی کتاب کا مقدمہ ہیں، کسی میں خاص موضوع سے متعلق تحقیق ہے، کوئی متعین منہج کے متعلق توضیحی رسالہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور بعض میں ایسی احادیث کو یکجا کیا گیا ہے جن کے ضمن میں کسی خاص منہج اور اس کے اِثبات کے معیارات کی پہچان ہوتی ہے۔ (۱۰)
یہ مرحلہ تقریباً چوتھی صدی ہجری کے آغاز سے شروع ہوتا اور چودھویں صدی ہجری کی ابتدا کے لگ بھگ ختم ہوتا ہے۔ اہلِ علم نے جیسے پچھلے مرحلے (مرحلۂ متقدّمین) کو تاریخی ادوار میں تقسیم کیا ہے، یہ مرحلہ بھی اُس تاریخی تقسیم کے تابع ہے؛ چنانچہ ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسبِ ذیل تین تاریخی ادوار میں تقسیم کیا ہے:
1- جامع تالیفات اور فنِ علومِ حدیث کی تدوین کے آغاز کا دور، جو چوتھی صدی ہجری کے نصف سے ساتویں صدی کے آغاز تک جاری رہا۔
2- فنِ علوم حدیث کی تدوین میں پختگی اور کمال کا دور، یہ دور ساتویں سے دسویں صدی تک پھیلا ہوا ہے۔
3- دورِ جمود، جو دسویں صدی سے چودھویں صدی کے آغاز تک جاری رہا۔(۱۱)
ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ اس پورے دورانیے کو ایک ہی دور قرار دیا ہے، جو تقریباً چوتھی صدی کے نصف سے شروع ہوتا ہے۔ (۱۲)
ڈاکٹر حاتم عونی حفظہ اللہ نے اس مرحلے کو دو ادوار میں تقسیم کیا ہے:
1- چوتھی صدی ہجری کا دور۔
2- پانچویں صدی ہجری اور اس کے بعد کا دور۔ (۱۳)
ان تمام ادوار کو ’’مرحلۂ متاخرین‘‘ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مرحلہ، قواعد کی تدوین اور نقدِ احادیث سے متعلق قوانین وقواعد کے ظہور کے اعتبار سے نمایاں ہے، اور ان امور کے وسائل درج ذیل ہیں:
1- ’’مرحلۂ متقدّمین‘‘ میں اہلِ علم کے کاموں کا تتبُّع۔
2- ان کے احوالِ زندگی کی جستجو۔
3- نقدِ حدیث کے متعلق ان کے طریقہ کار کی تحقیق۔
1- یہ مرحلہ دو قسم کی تصانیف کے اعتبار سے ممتاز ہے:
نوعِ اول: تحقیق وتمییز کے آغاز کے موافق احادیث ومرویّات کو یکجا کرتی کتب۔ یہ عمل پچھلے مرحلے (مرحلہ متقدّمین) میں کیے گئے کاموں کے تکملے اور ان کی بنیاد پر بعض دیگر کاموں کے لیے تاسیس کی حیثیت رکھتا ہے، تاہم بعض حدیثی کتب ان کے علاوہ بھی ہیں۔
نوعِ دوم: قواعد اور سلف کے ایسے احوال کی تدوین، جو ان کے منہجِ نقدِ حدیث سے متعلق ہوں۔ اس مرحلے میں قواعد کی تدوین، اسانید کے ساتھ روایت ہوتی تھی، اور یہ سلسلہ یونہی جاری رہا، یہاں تک کہ علمِ مصطلح، ہمارے پیشِ نظر قواعد کی صورت میں بغیر سندوں کے سامنے آیا، جیسے حافظ ابن صلاح اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ کی کتابوں میں دکھائی دیتا ہے۔
2- اس مرحلے کا ایک اہم امتیاز ’’تصحیح وتضعیف کے باب میں اجتہاد کا دروازہ بند کرنا‘‘ ہے۔ حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ’’علوم الحدیث‘‘ (مقدّمۃ ابن الصلاح) (۱۴) میں امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ سے اخذ کرتے ہوئے اس جانب اشارہ کیا، اور خود حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس طرف واضح میلان ہے، (۱۵) لیکن ان کے بعد بیشتر اہلِ علم نے، اور خاص طور پر ’’مقدمۃ ابن الصلاح‘‘ کے شارحین، مُعلّقین، مُنَکّتین (أصحابُ النِّکَت) اور ناظمین (مقدّمۃ ابن الصلاح کو نظمانے والے اہلِ علم) نے اس موقف میں حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے۔ (۱۶)
بہرکیف! اس مرحلے میں گوناگوں تحقیقات ظہور پذیر ہوئیں، ان میں سے بعض میں باسند اخبار کی صورت میں قواعد کا ذکر ہے، اور بعض میں بلاسند صرف قواعد کا تذکرہ ہے۔ اور بلاسند قواعد میں بھی کہیں محض حدیثی اصطلاحات وانواع کا تذکرہ ہے، اور کسی کتاب میں ایک مستقل منہج اور نظام کا بیان ہے جو ان اصطلاحات کے باہمی ربط وتعلّق کو مستحکم صورت میں پیش کرتا ہے۔
یہ مرحلہ تقریباً چودھویں صدی ہجری کے آغاز سے شروع ہوا، اور دورِ حاضر تک جاری ہے۔ ایک تاریخی دور ہونے کی حیثیت سے ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ نے خاص طور پر اس مرحلے کا تذکرہ کیا ہے، انہوں نے اس مرحلے کا اس حیثیت سے ذکر کیا ہے کہ یہ مرحلہ، عہدِ حاضر میں (علومِ حدیث کے تعلق سے) بیداری اور تیقُّظ کی نئی لہر کا نمائندہ ہے، اور دسویں صدی ہجری سے چودھویں صدی کے آغاز تک جاری دورِ جمود کے مقابلے میں ہے۔ تاہم ڈاکٹر اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مرحلہ، چوتھی صدی کے نصف سے جاری تیسرے دور کا ہی تسلسل ہے، جبکہ ڈاکٹر عونی حفظہ اللہ کی رائے میں یہ پانچویں صدی سے شروع ساتویں دور کا حصہ ہے۔
اس مرحلے کو مستقل طور پر ذکر کرنے اور ’’مرحلۂ متاخرین‘‘ کا تسلسل قرار نہ دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس مرحلے میں منہج کی ساخت میں بہت سے نئے افکار سامنے آئے ہیں، جن کے نتیجے میں متعدد تالیفات مرتب ہوئیں، یہ کتابیں علمِ حدیث کی تاریخ میں اس مرحلے کے خصوصی تذکرے کی متقاضی ہیں۔ اس کے برخلاف ’’مرحلۂ متاخرین‘‘ میں علمی وسعت تو ہوئی، لیکن نمایاں طور پر اس کی بنیاد (مرحلۂ متقدمین میں لکھی گئی) سابقہ کتابیں تھیں، لہٰذا ’’مرحلۂ معاصرین‘‘ واضح حدود پر مشتمل جدا مرحلہ ہے، جو اگرچہ علمی ساخت کے لحاظ سے سابقہ ذخیرہ کی بنیاد پر وجود میں آیا ہے، لیکن اسلوبِ عرض (وبیانِ مباحث) کے اعتبار سے یہ مرحلہ سابقہ مراحل سے مختلف ہے۔
اس مرحلے کی جداگانہ خصوصیات کو پیشِ نظر رکھنے سے اس کی انفرادیت واضح ہوتی ہے؛ کیونکہ اس دور میں متعدّد نئے مباحث وجود میں آئے ہیں، مثلًا:
1- ذخیرۂ سنت کی جانب مغرب کی ’’خصوصی توجہات‘‘ کی بنا پر علمِ مصطلح کے مباحث کے متعلق استشراقی نظریات کا ظہور۔
2- علمِ مصطلح کے متعلق مغربی افکار کا ناقدانہ تجزیہ، ان کی تردید اور ان کے تار وپود بکھیرنا۔
3- نقدِ متن (حدیث) کی بحث۔
اس (تیسرے) مسئلے کا پہلے مسئلہ سے بلا واسطہ ربط ہے؛ کیونکہ ان دونوں بحثوں کے نتیجے میں علمِ مصطلح کے متعلق جدید مباحث سامنے آئے، یا (بالفاظِ دیگر) جدید اسلوب میں قدیم مباحث کی تحقیق کا رجحان پیدا ہوا۔
4- انسانی علوم کے مناہج کا قضیہ، اور دینی نصوص کے تجزیہ (اِثبات اور تاویل) میں ان کا کردار۔
عالمِ اسلام عمومی طور پر عصرِ حاضر میں جس مرحلے سے گزر رہا ہے، اجمالی طور پر اس کی اہم خصوصیات یہی ہیں۔
چودھویں صدی کے آغاز سے ہی عالمِ اسلام کی تاریخ میں کئی بڑے انقلابات آئے، ان میں سب سے اہم واقعہ خلافتِ عثمانیہ کا سقوط، اس کے نتیجے میں نئے عرب ممالک کا قیام، اور پھر اس کے پہلو بہ پہلو مشرقِ ناتواں کی جانب مغرب کی ’’گہری توجہات‘‘ ہیں؛ کیونکہ مغرب تین صدیوں سے زمانے کے ساتھ ایک دشوار جنگ لڑ رہا تھا، سترہویں صدی عیسوی میں (مغرب کے) تابناک دور کا آغاز ہوا، تشکیکی ذہنیت کی شروعات ہوئیں، جس کی بنیاد خاص طور پر (فرانسیسی فلسفی اور ریاضی دان) ڈیکارٹ (Rene Descartes) [۱۵۹۶ء-۱۶۵۰ء] نے رکھی تھی، اور تشکیکی سوالات کے نتیجے میں سابقہ دینی، معاشرتی اور سیاسی نظام پر نظرِ ثانی کی جانے لگی، اور اسی بنا پر منہج کا قضیہ سامنے آیا اور جدید سائنسی علوم کی بنیاد پڑی، نظریۂ انفرادیت واجتماعیت پر مبنی فلسفے ظہور پذیر ہوئے، اور ان کی کُوکھ سے متعدد نظریات نے جنم لیا، کارل پوپر (Karl Popper) [۱۹۰۲ء-۱۹۹۴ء] اور فرانسیس بیکن (Francis Bacon) [۱۵۶۱ء-۱۶۲۶ء] نے بحثِ استقراء اور سائنسی طریقہ کار کی ساخت کا مسئلہ اُبھارا، اور ادبی تنقید کے اسالیب کے میدان میں نظریۂ ساختیات (Structuralism) اور نظریہ ردّ تشکیلیت (Deconstruction) وجود میں آئے، ان نظریات کی نسبت سے خاص طور پر (فرانسیسی فلسفیوں) رولان بارتھس (Roland Barthes) [۱۹۱۵ء-۱۹۸۰ء] اور ژاک دریدا (Jacques Derrida) [۱۹۳۰ء-۲۰۰۴ء] کی شہرت ہوئی، جدید انسانی فلسفہ کے میدان میں مغربی فلاسفہ: نٹشے (Friedrich Nietzsche) [۱۸۴۴ء-۱۹۰۰ء] وغیرہ نے نظریۂ جدیدیت وما بعد جدیدیت پیش کیا۔
مذکورہ نظریات اور مباحث کی بنا پر ایک نظریۂ تعلیم وجود میں آیا، جس میں تشکیکی سوالات، تنقیدی اسلوب اور معروضیت پر مبنی آزادانہ تحقیق ہو، اور پیشگی معلومات کی قید سے جاں خلاصی ہو، بلکہ کسی نص یا مطالعہ کردہ مواد پر ایمان سے بھی ہاتھ دھو لیے جائیں۔ (أعاذنا اللہ منہ)
اس نقطۂ نظر نے اہلِ مغرب کے نزدیک شخصی آزادی سے ایمانی مباحث تک ہر عقیدہ ونظریہ کو موضوعِ بحث بنا دیا، خاص طور پر دینی نص (قرآن وحدیث) پر اکیڈمک اسلوب میں تحقیق کی جانے لگی۔ تحریکِ استشراق اسی ’’تحقیقی جدوجہد‘‘ کا ایک حصہ ہے۔ مستشرقین نے منہج کے مسئلہ کی وجہ سے اس کی بنیاد ڈالی، اور اسی اساس پر مستشرقین، مشرق (یعنی اہلِ مشرق اور مشرقی علوم، جن میں علومِ اسلامیہ بھی شامل ہیں) کی تحقیق کی جانب متوجہ ہوئے، کبھی علمی اور معروضی وسائل کے ذریعے (ایسا شاذ ونادر ہی ہوا)، کبھی سابقہ نظریات کے بغیر جدید ذرائع کے واسطے سے (اکثر وبیشتر یہی طرزِ عمل رہا)، اور کبھی ادبی وفنی ہتھیاروں کے ذریعے ایک خیالی اور خوابوں کی دنیا کی صورت میں مشرق کی تصویر کشی کرتے ہوئے (دادِ تحقیق دی جانے لگی)۔
مغربی مستشرقین کے ان کارناموں کے مقابلے کے لیے عالمِ اسلام کے اہلِ علم تحریکِ استشراق کے اغراض ومقاصد، ان کی فکری بنیادوں، اور دور رس مقاصد کے ادراک کے لیے کمر بستہ ہوئے، علماء اسلام کی بعض تحقیقات دفاعی اور معذرت خواہانہ تھیں (جیسے بیشتر مستشرقین کا بھی یہی حال ہے) ، جن میں (مستشرقین کے) شبہات کا تفصیلی جواب دیا گیا، لیکن مغربی منہج پر تنقید نہیں کی گئی، بعض تحقیقات معروضی ہیں (مستشرقین میں بھی بہت کم ایسے ہیں) ، اور بعض گہری اور بعض آسان وسادہ اسلوب میں ہیں۔ (۱۷)
یہاں یہ نکتہ ذکر کرنا اہم ہوگا کہ تحریکِ استشراق اس علم (علمِ حدیث) کے ڈھانچے میں ایک ٹھوس تبدیلی کا باعث بنی ہے، اور اس تبدیلی کا آغاز چودھویں صدی ہجری کی ابتدا سے ہوا، وہ یہ کہ علمِ مصطلح سے متعلق کئی کتابوں میں استشراق کے موضوع کو اہمیت دی جانے لگی، نتیجتاً دورِ حاضر میں دو رُجحانات سامنے آئے ہیں:
۱- مستشرقین کی کتابوں کا تجزیہ وتنقید۔
۲- (بعض) مسلمان اہلِ علم کے علمی کاموں میں جدید مغربی یونی ورسٹیوں میں رائج منہج سے بالواسطہ تأثر۔ یہ نکتہ اگلے صفحات میں واضح ہوگا۔
معاصر کتب میں لفظِ ’’منہج‘‘ کا مفہوم دو انداز سے استعمال ہوا ہے:
پہلا انداز: متعین اسلوب کے مطابق (قدیم مباحث کی) دوبارہ ترتیب اور تنظیم۔
دوسرا انداز: کسی منہجی بحث اور مسئلے پر نظرِ ثانی۔
ملاحظہ کیجیے کہ دورِ حاضر میں معاصرین کے کاموں کے ایک مجموعے میں منہج کے مسئلہ سے اعتنا کیا گیا ہے، خواہ ترتیب کا اعادہ ہو یا (کسی بحث پر) نظرِ ثانی۔ اس سے بڑھ کر بعض معاصرین نے علمِ مصطلح سے متعلق کتابوں کے عنوان میں بھی لفظِ ’’منہج‘‘ ذکر کیا ہے، جیسے: ’’منہج النقد‘‘ ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ ، ’’منہج النقد عند المحدّثين‘‘ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ، ’’المنہج الحديث في علوم الحديث‘‘ ڈاکٹر محمد محمد سماحی رحمۃ اللہ علیہ ، بعد ازاں انہی علماء کی راہ پر گامزن اہلِ علم، جیسے: ڈاکٹر حاتم عونی حفظہ اللہ کی کتاب ’’المنہج المقترح‘‘، اور راقمِ سطور کی کتاب ’’منہج قبول الأخبار عند المحدّثين۔ ‘‘
علمِ حدیث کی طرح ’’نقدِ متن‘‘ کا قضیہ بھی قدیم ہے، لیکن دورِ حاضر میں اور خاص طور پر چودھویں صدی ہجری کے نصف کے بعد یہ قضیہ نئی صورتوں میں سامنے آیا ہے۔ ’’نقدِ متن‘‘ کا مسئلہ دو صورتوں میں جلوہ گر ہوا ہے:
1- استشراقی نقطۂ نظر کی تنقید کی صورت میں۔
2-’’نقدِ متن‘‘ کے مفہوم کی بنیادی صورت میں۔
پہلی صورت میں یہ بحث‘ اہلِ علم کی ان علمی تنقیدوں کے ضمن میں آئی ہے جو (’’نقدِ متن‘‘ کے) استشراقی مفہوم اور محدثین کے ہاں ’’نقدِ متن‘‘ کے تعلق سے استشراقی موقف کے خلاف لکھی گئی ہیں، جیسے: ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ’’السنۃ ومکانتہا في التشریع الإسلامي‘‘، ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ’’منہج النقد‘‘، اور ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں ’’منہج النقد عند المحدّثين‘‘ اور ’’دراسات في الحديث النبوي‘‘ وغیرہ۔
دوسری صورت میں بعض تحقیقات کی بنیاد پڑی، جن میں ’’نقدِ متن‘‘ کے تناظر میں قابلِ اتباع طریقہ واضح کیا گیا ہے۔ (۱۸)
اس انتہا درجہ اہتمام کے دو اسباب ہیں: داخلی اور خارجی۔ دوسرا سبب پہلے سے زیادہ مؤثّر ہے؛ کیونکہ خارجی سبب، علمِ اصولِ حدیث پر استشراقی تنقید اور محدثین کے متعلق ان کی تنقید ( کہ انہوں نے سندوں کی تحقیق کی، لیکن متون کی تحقیق کا اہتمام نہیں کیا) کے گرد گھومتا ہے۔ جبکہ داخلی سبب یہ ہے کہ بہت سے طلبۂ علم کی جانب سے علمِ مصطلح کو دورِ حاضر کے تقاضوں کے ہم آہنگ کرنے کا کافی اہتمام دکھائی دیتا ہے، اس کے نتیجے میں بہتیری مشکل احادیثِ نبویہ کی تحقیق کی گئی، اور انہیں محض دورِ حاضر کے تقاضوں کے مخالف ہونے کی بنا پر ضعیف یا مردود قرار دیا گیا۔
معاصر مرحلے میں علمِ مصطلح کے متعلق بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بیشتر کتب اس علم کی تسہیل اور طلبۂ علم کے سامنے آسان صورت میں پیش کرنے سے متعلق ہیں۔ تصانیف کا ایک مجموعہ، صورت یا مضمون یا دونوں کے اعتبار سے ممتاز ہے۔ ان تصانیف میں سے چند درجِ ذیل ہیں:
۱- ’’قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث‘‘ شیخ جمال الدین قاسمی رحمۃ اللہ علیہ ۔
۲- ’’توجيہ النظر إلی أصول الأثر‘‘ شیخ طاہر جزائری رحمۃ اللہ علیہ ۔
۳- ’’قواعد في علوم الحديث‘‘ محدث ظفر احمد عثمانی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ۔
۴- ’’السنۃ ومکانتہا في التشریع الإسلامي‘‘ ڈاکٹر مصطفی سباعی رحمۃ اللہ علیہ ۔
۵- ’’منہج النقد‘‘ ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ ۔
۶- ’’منہج النقد عند المحدّثين- نشأتہ وتاريخہ‘‘ ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ ۔
۷- ’’المنہج المقترح لفہم المصطلح- دراسۃ تأريخيۃ تأصيليۃ لمصطلح الحديث‘‘ ڈاکٹر حاتم عونی حفظہ اللہ۔ (۱۹)
۸- ’’علوم الحديث في ضوء تطبيقات المحدّثين‘‘ ڈاکٹر حمزہ ملیباری حفظہ اللہ۔
ان کتابوں کے سرسری جائزہ سے مرحلۂ معاصرین کو مستقل طور پر ذکر کرنے اور اسے مرحلۂ متقدّمین و مرحلۂ متاخرین کا قَسِیم قرار دینے کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ اس مرحلے (کے مذکورہ تمام امتیازات) کے ساتھ علمِ مصطلح ایک ایسے منہجی مرحلے میں داخل ہوچکا ہے جو ماضی سے ممتاز ہے۔
قبل ازیں علمِ حدیث، عالمِ اسلام کے علمی حلقوں کے درمیان دائر ایک علم تھا، اس علم کا حامل محض اجازات کے بل بوتے ہی آگے پہنچانے (اور تعلیم دینے) کا اہل ہوجاتا تھا، اب یہ علم (مذکورہ خصوصیات کے ساتھ ساتھ) کلیاتِ شرعیہ میں ایک علمی مستقل شاخ بن گیا ہے، جن میں (علومِ حدیث میں مہارت کے حامل) سند یافتہ اساتذہ کی مرتب کردہ جدید تالیفات پڑھائی جاتی ہیں، اور ان ماہرین کو یہ سندیں تقریباً متفقہ اکیڈمک معیار کے موافق بحث وتحقیق کی بنیاد پر حاصل ہوتی ہیں۔ نیز اب تاریخی منہج اور نظریۂ علمیّات (Epistemology) کے متخصّص انسانی علوم کے مناہج بھی خبروں کی چھان پھٹک کی غرض سے علمِ مصطلح (کے قواعد و ضوابط) سے استفادہ کرتے ہیں، اور سماجیات ونفسیات کے ماہرین، راویوں کی جرح وتعدیل کے تعلق سے علمِ مصطلح سے فائدہ اُٹھاتے ہیں۔ (والفضل ما شہدتْ بہ الأعداء!)
تاریخِ اسلام نے ابتدا میں ہی متعدّد اسلامی تہذیبوں کی شناخت حاصل کی، جن میں روایتِ حدیث کے ابتدائی تُخم کی نشوونما ہوئی۔ ابتدا میں سندوں کا مرکز، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ تھے، متعدّد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عراقی شہروں (کوفہ، بصرہ اور بغداد) منتقلی سے یہ مرکزیّت عراق میں منتقل ہوگئی۔ فتنوں کے پیش آنے کے بعد سند کا مطالبہ نُمایاں ہوگیا، امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا:
’’لم يکونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنۃ قالوا: سمّوا لنا رجالکم؛ فينظر إلی أہل السنۃ فيؤخذ حديثہم، وينظر إلٰی أہل البدع، فلايؤخذ حديثہم۔‘‘ (۲۰)
یعنی ’’(ابتدا میں)اسناد کے بارے میں سوال نہیں کرتے تھے، جب فتنہ پیش آگیا تو انہوں نے کہنا شروع کیا: ہمارے سامنے اپنے رجال (حدیث) کے نام ذکر کرو؛ تاکہ اہلِ سنت کو دیکھ کر اُن سے حدیث لی جائے اور اہلِ بدعت کو دیکھ کر اُن کی حدیث قبول نہ کی جائے۔‘‘
بعد ازاں جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ایک تعداد شام منتقل ہوگئی، تو ان صحابہ کرامؓ اور خلافتِ امویہ (جس نے اپنے خلیفہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے ذخیرۂ سنت کی سرکاری تدوین کی بنیاد ڈالی تھی) کی بدولت یہ نئی روایت (طلبِ اسناد) شام میں بھی منتقل ہوگئی۔
خلافتِ امویہ کے ذریعے مرکزِ اسلام کے شام منتقل ہونے کے بعد تاریخِ اسلام میں کئی بڑے واقعات پیش آئے اور کلامی فرقے پیدا ہوئے۔ مسئلہ تقدیر اور عدلِ الٰہی کے تعلق سے مختلف کلامی مذاہب کی بنیاد پڑی، ان میں ایک اہم فرقہ ’’معتزلہ‘‘ ہے، جن کا نام بعد میں ’’قدریہ‘‘ پڑ گیا، اور خاص ’’قدریہ‘‘ کا نام ’’مجبرہ‘‘ تھا۔(۲۱) ’’مجبرہ‘‘ امویوں کے تابع تھے۔ ’’مرجئہ‘‘ کی اکثریت اور ’’خوارج‘‘ بھی شام میں تھے۔ ان کلامی فرقوں کی بنا پر ’’قدر وابتداع‘‘ اور راوی ومروی کی تحقیق کے تئیں نُمایاں اختلافات پیش آئے، چنانچہ ’’قدر‘‘ اور ’’ارجاء‘‘ کسی راوی کی جرح وتعدیل اور اس کی روایت کی قبولیت کے متعلق ایک بنیادی علامت اور نُمایاں صفت بن گئی۔ (۲۲)
مذکورہ صورتِ حال کے نتیجے میں ’’منہجِ نقدِ احادیث واخبار‘‘ کے متعلق پہلی تین صدیوں میں تین بنیادی مذاہب سامنے آئے:
1- مذہبِ معتزلہ: معتزلہ کا مرکز عراق تھا، اور یہیں سے وہ اس دور میں عالمِ اسلام کی متعدّد تہذیبوں میں پھیلے، مثلًا: بلخ، اور مغربِ اقصی۔ (۲۳) شام میں اُموی ان کے مخالف تھے۔
مذہبِ اعتزال کی بنیاد پانچ کلامی مسائل ہیں: توحید، عدل، منزلہ بین المنزلتین، وعدہ ووعید، امر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ معتزلہ ان پانچ امور پر متفق ہیں، اور ’’نقدِ احادیث واخبار‘‘ میں انہیں اَساس قرار دیتے ہیں، چنانچہ جو احادیث ان پانچ بنیادوں کے موافق ہوں وہ ان کے نزدیک صحیح احادیث ہیں، اگرچہ وہ مدوّن ذخیرۂ سنت میں ضعیف، بلکہ موضوع ہی کیوں نہ ہوں۔ اور جو احادیث ان پانچ بنیادی مسائل کے موافق نہ ہوں، اگر وہ متواتر ہوں تو معتزلہ ان میں تاویل کرتے ہیں، اور اگر اخبارِ آحاد صحیحہ ہوں تو انہیں رد کردیتے ہیں۔
2- مذہبِ حنفی: جو اپنے مخالفین یعنی اہلِ حدیث کے نزدیک مذہبِ اہلِ رائے سے معروف ہے، اس کا مرکز بھی عراق تھا، اور وہاں سے بلادِ ما وراء النہر تک پھیلا۔
(امام) عیسیٰ بن ابان اور متقدمین ومتاخرین حنفیہ میں سے ان کے متبعین نے مذہبِ حنفی میں قیاس کو ایسی خبر واحد پر مقدم رکھا ہے جس کا راوی عادل ہو، لیکن فقیہ نہ ہو، جبکہ (اس خبر واحد پر عمل سے) رائے واجتہاد کی راہیں بند ہوتی ہوں۔ (۲۴)
3- مذہبِ مالکی: جو عملِ اہلِ مدینہ کو خبر واحد صحیح پر مقدم رکھنے میں معروف ہے۔
4- مذہبِ محدثین: جو عمومًا مذہبِ شافعی ومذہبِ حنبلی کے متبعین پر مشتمل ہے، انہوں نے قبولِ حدیث میں راوی کی عدالت کو اَساس قرار دیا ہے۔
مسئلہ قدر، خوارج اور تشیّع (یعنی وہ امور جن کی بنا پر راوی مجروح قرار پاتا ہے اور اس کی روایت مردود) کے متعلق اس دور میں بلادِ شام نے جو کلامی موقف اختیار کیا تھا، اس کے بارے میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ مذہبِ محدثین (جس کی بنیاد عدالت کو معیار قرار دینے پر ہے) ایسی چھتری ہے جس کے ذریعے ہم اس دور کے بلادِ شام کا منہج پہچان سکتے ہیں، اگرچہ بلادِ شام کی احادیث کے متعلق یہ وصف بھی ملتا ہے کہ یہ احادیثِ رقائق ومواعظ کے بلاد ہیں۔
بنیادی طور پر منہجِ محدثین ہی بعد کے دور کی ابتدائی کتب میں علمِ اصولِ حدیث سے معروف ہوا، ابتدا میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا ’’مقدمۃ صحیح مسلم‘‘، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی ’’العلل الصغیر‘‘، اور ’’رسالۃ الإمام أبي داود إلٰی أھل مکۃ‘‘، درمیانی دور میں ’’مقدمۃ ابن الصلاح‘‘ اور آخر میں حافظ حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ’’نزہۃ النظر‘‘، نیز ان دونوں شخصیات (یعنی حافظ ابن صلاح اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ) کی کتابوں کی شرحیں، تعلیقات، مختصرات اور منظومات۔
چنانچہ محدثین (خاص طور پر مذہبِ شافعی ومذہبِ حنبلی) بعد کے مرحلے میں چوتھی صدی کی ابتدا سے تا حال علمِ مصطلحِ حدیث کی بنیاد بنے۔ معتزلہ کے کلامی مذہب اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے علاوہ ’’نقدِ احادیث‘‘ کے متعلق دونوں طبقوں کے حدیثی مذہب کاعلمی رواج اور پھلنا پھولنا مقدر نہ ہوا۔
لیکن عین اسی دور میں مذہبِ حنفی کے نقطۂ نظر سے اصطلاحی کتابیں موجود ہیں، دورِ حاضر میں اس حوالے سے علماء ہند کا اہم کردار ہے، جیسے: مولانا ظفر احمد عثمانی تھانوی اور مولانا عبد الحی لکھنوی رحمہما اللہ وغیرہ کی کتابیں۔ اس کے بعد یہ کتب اس بنا پر تصنیف کی گئیں کہ یہ کتابیں، متاخرین کے ایک ہزار سال (چوتھی سے تیرہویں صدی) کے دوران علمِ مصطلح الحدیث کی طویل روایت کی نمائندگی نہیں کرتیں۔
۱- ملاحظہ کیجیے: ’’نشأۃ علم المصطلح والحدّ الفاصل بين المتقدّمين والمتأخرين‘‘، فصلِ دوم، ڈاکٹر عصام عیدو (ص : ۸۱ اور اس کے بعد)
۲- دیکھیے: ’’منہج النقد‘‘ (ص: ۳۷ - ۶۳)
۳- ملاحظہ کیجیے: ’’منہج النقد عند المحدّثين‘‘ (ص :۷،۸)
۴- دیکھیے ڈاکٹر حاتم عونی کا مقالہ: ’’بيان الحدّ الذي ينتہي عندہٗ أہل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث‘‘، یہ مقالہ مرکز الدراسات الإسلامیۃ، دبئی میں ’’علوم الحدیث - واقع وآفاق‘‘ کے عنوان سے منعقدہ سیمینار (کے شائع شدہ مقالات) کے ضمن میں طبع ہوا ہے۔ (ص :۴۰ - ۵۷)
۵- ڈاکٹر نور الدین عتر نے ان دو حیثیتوں کا لحاظ رکھا ہے۔
۶- ڈاکٹر حاتم عونی نے اپنی تقسیم میں اسی پہلو کو بنیاد بنایا ہے۔
۷- ڈاکٹر اعظمی نے اپنی تقسیم میں اس جہت کا اعتبار کیا ہے۔
۸- امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوبکر بن حزم رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا: ’’ مَا کَانَ مِنْ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَيْہِ وَسَلَّمَ فَاکْتُبْہُ ؛ فَإِنِّيْ خِفْتُ دُرُوْسَ الْعِلْمِ وَذَہَابَ الْعُلَمَاءِ‘‘ یعنی ’’آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث لکھ لیجیے؛ کیونکہ مجھے علم کے مٹنے اور اہلِ علم کے اُٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔ ‘‘ صحيح البخاري، کتاب العلم، باب: کيف يقبض العلم؟(۱/ ۴۸، ۴۹) امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہ حدیث تعلیقًا نقل کی ہے، بعد ازاں علاء بن عبد الجبار کے طریق سے ذکر کی ہے۔
۹- دیکھیے: ’’لمحات موجزۃ في أصول علم علل الحديث‘‘ ڈاکٹر نور الدین عتر، (ص:۱۹) اور مقدّمۃ المحقّق علٰی کتاب ’’العلل ومعرفۃ الرجال‘‘ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ، (۱/ ۳۴)
۱۰- ملاحظہ فرمائیے: ’’منہج النقد‘‘ ڈاکٹر عتر، (ص: ۶۲)
۱۱- دیکھیے: ’’منہج النقد‘‘ (ص: ۶۳- ۷۰)
۱۲- دیکھیے:’’منہج النقد عند المحدّثين‘‘ (ص: ۸)
۱۳- ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر حاتم عونی کا مقالہ: ’’بيان الحدّ الذي ينتہي عندہٗ أہل الاصطلاح والنقد في علوم الحديث‘‘ (ص: ۵۸ - ۷۴)
۱۴- (ص: ۱۱، ۷۰، ۷۱)
۱۵- ’’مقدمۃ ابن الصلاح‘‘ کی نوعِ اول کے دوسرے فائدے میں حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس نکتے کا ذکر کیا ہے، حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سے آج تک اہلِ علم میں یہ عبارت موضوعِ بحث رہی ہے۔ حال میں ’’دارالبشائر الإسلامیۃ‘‘ بیروت سے ایک عرب خاتون ڈاکٹر ایمان بنت محمد علی عزام کی کتاب شائع ہوئی ہے: ’’مسألۃ التصحیح في الأعصار المتأخرۃ- بین کلام ابن الصلاح رحمہ اللہ وتعلیقات العلماء ودراسات المعاصرین‘‘ کے نام سے ۳۹۲ صفحات پر مشتمل اس کتاب میں اس موضوع کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ متخصصینِ علوم حدیث کو اس کتاب سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے، اور زیربحث مسئلے کی تحقیق کے ساتھ کسی اصولی بحث کا طریقۂ تحقیق بھی اس کتاب کے ذریعہ سیکھنا چاہیے، نیز ’’أحکام الحافظ ابن الصلاح علی الأحادیث- جمعاً و دراسۃ مقارنۃ‘‘ کے نام سے شیخ خالد فیتوری کی ایک کتاب تین جلدوں میں دارالریاحین (عمان، اردن) سے شائع ہوئی ہے، جس پر حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے لگائے گئے احکام پر مشتمل احادیث یکجا کردی گئی ہیں، اس کتاب پر معروف عرب محدّث اور جامعہ ازہر کے استاذ ڈاکٹر احمد معبد عبدالکریم حفظہ اللہ کا گراں قدر مقدمہ ہے۔ یہ دونوں معاصر کتابیں حافظ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نظر کو واضح کرنے کے لیے اہم اور مفید اضافہ ہیں۔ (از مرتب)
۱۶- دیکھیے: ’’إرشاد طلّاب الحقائق‘‘ للنوويؒ(ص ۶۶)، ’’شرح التبصرۃ والتذکرۃ‘‘ للعراقي(۱/ ۱۳۰) اور ’’تدريب الراوي‘‘ للسيوطيؒ(۱/ ۱۵۴ - ۱۶۰)
۱۷- ملاحظہ کیجیے ڈاکٹر مصطفیٰ سباعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں: ’’الاستشراق‘‘ اور ’’السنۃ ومکانتہا في التشريع الإسلامي‘‘، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ’’دراسات في الحديث النبوي‘‘، ڈاکٹر نور الدین عتر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ’’منہج النقد‘‘، اور ڈاکٹر حاکم مُطیری کی کتاب ’’تاريخ تدوين السنۃ وشبہات المستشرقين‘‘ ۔ مذکورہ کتابوں میں سے بعض میں آپ کو گہرائی نظر آئے گی، جیسے: ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں، اور بعض میں گہرائی کے ساتھ واضح ردّ عمل بھی دکھائی دے گا جس میں مستشرقین کے منہج کو ایسے شکوک وشبہات کا مجموعہ قرار دیا گیا ہے جو بلا تحقیق وتجزیہ پیش کیے گئے ہیں۔
۱۸- جیسے: کتاب ’’السنۃ النبويۃ بين أہل الفقہ وأہل الحديث‘‘ ڈاکٹر محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ ، اور اس کتاب پر لکھی گئی تنقیدی کتب ورسائل۔
۱۹- یہ کتاب دراصل ڈاکٹر حاتم عونی حفظہ اللہ کی ایک اور کتاب ’’المرسل الخفي وعلاقتہ بالتدليس‘‘ کا تمہیدی مقدمہ ہے، جو مستقل کتاب کی صورت میں شائع ہوا ہے، اور حدیثی منہج کے متعلق نہایت اہم مباحث پر مشتمل ہے۔
۲۰- یہ قول امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ’’صحیح مسلم‘‘ کے مقدمہ (۱/ ۱۵) میں نقل کیا ہے، نیز دیکھیے: ’’الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع‘‘ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ (۱/ ۱۹۶) فقرہ نمبر: (۱۴۴)، اور ’’شرح العلل‘‘ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ (۱/ ۵۲، ۵۳)
۲۱- دیکھیے: ’’فضل الاعتزال‘‘ قاضی عبد الجبار معتزلی (ص: ۳۴۵)
۲۲- ملاحظہ کیجیے: ’’قبول الأخبار ومعرفۃ الرجال‘‘ ابو القاسم عبد اللہ کعبی بلخی (۲/ ۳۸۱ اور اس کے بعد)
۲۳- دیکھیے: ’’مقالات الإسلامیین‘‘ بلخی (ص: ۷۵ اور اس کے بعد)
۲۴- ملاحظہ فرمائیے: ’’أصول السرخسي‘‘ (۱/ ۳۳۸، ۳۳۹)، ’’تقويم أصول الفقہ‘‘ للدبوسي(۱/ ۳۰۸)، ’’أصول البزدوي‘‘ (۲/ ۶۹۸، ۶۹۹)، ’’کشف الأسرار‘‘ لعلاء الدين البخاري(۲/ ۲۹۹)، اور ’’شرح المنار‘‘ (ص:۲۰۹- ۲۱۱)