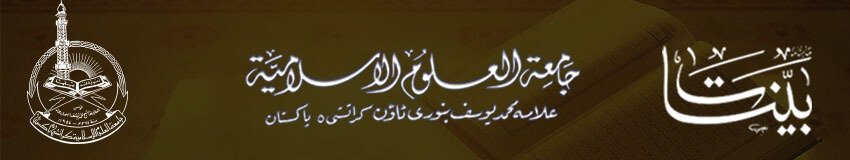
علومِ حدیث کے استعمال میں اِفراط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اجماعیات اور مسلّمات کا بھی انکار کر بیٹھتے ہیں ، مثلاً:
1-بعض لوگ عقیدہ نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں ، جیسے: مصر کے شیخ ابوزہرہ رحمۃ اللہ علیہ کسی دور میں نزولِ عیسیٰ علیہ السلام کے قائل نہیں تھے، چوں کہ محتاط آدمی تھے، اس لیے غالباً اس موضوع کے متعلق کوئی کتاب نہیں لکھی، بس ان کے ذہن میں ایک بات آگئی، شاید ا ن کی نظر میں چند ایسی روایات ہوں جن پر کلام ہو، او رمکمل تحقیق کا موقع نہ مل سکا، اس لیے ذہن میں یہی نظریہ بن گیا۔ جب شیخ عبدالفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق سے ’’التصریح بما تواتر في نزول المسیح علیہ السلام‘‘ شائع ہوئی تو شیخ عبدالفتاح رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک نسخہ، شیخ ابوزہرہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہدیہ بھیجا، شیخ نے کتاب کے مطالعہ کے بعد شیخ عبدالفتا ح کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ: ’’ ا ب میری رائے بدل گئی ہے، میرے علم میں نہیں تھا کہ اس بارے میں اس قدر صحیح احادیث موجود ہیں ۔ ‘‘
2-شیخ محمود شلتوت نے عقیدہ نزولِ مسیح علیہ السلام کے انکار میں ایک کتاب لکھی، جس کے رد میں شیخ کوثری رحمۃ اللہ علیہ نے ’’نَظْرَۃٌ عَابِرَۃٌ فِيْ مَزَاعِمِ مَنْ یُّنْکِرُ نُزُوْلَ عِیْسٰی قَبْلَ الْآخِرَۃِ‘‘ لکھی۔
3-امام مہدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو روایات ہیں ، ان میں سے بعض میں کچھ کلام ہے، ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات پر کلام دیکھا تو سارا کلام نقل کردیا، اور اُسلوب ایسا اختیار کیا کہ گویا وہ خود بھی خروجِ مہدی کے منکر ہیں ۔ (ملاحظہ کیجیے: مقدمۃ ابن خلدون، الفصل الثاني والخمسون، ص:۳۱۱، ۳۱۲)
یہاں یہی وہم ہوا کہ جرحِ روات کا غلط اور بے موقع استعمال کیا، ابن خلدون کے اس وہم کے رد میں بھی مستقل رسائل لکھے گئے ہیں : ایک کتاب ’’إبراز الوہم المکنون من کلام ابن خلدون‘‘ ہے، یہ شیخ احمد بن صدیق الغماری رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، میں نے اس کا مطالعہ نہیں کیا۔ دوسرا رسالہ حضرت حکیم الامت مولاناا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو امداد الفتاویٰ (ج: ۶، ص: ۲۴۷-۲۵۵) میں چھپا ہوا ہے، نہایت قابلِ مطالعہ ہے۔
یہ سب علومِ حدیث کی تطبیق میں افرا ط کے نتائج ہیں کہ مسلّمات اور اجماعیات کا بھی لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں ۔
الغرض علومِ حدیث کا افراط پر مبنی استعمال تو یہ ہوا کہ جرحِ معلول، اعلالِ مجروح، علتِ غیر قادحہ، بلکہ جرحِ مختلف فیہ یا علتِ مختلف فیہاکو بہانہ بنا کر کسی ایسی حدیث کو رد کر دیا جائے جو امت میں مُتَلَقّٰی بالقبول ہے، یا محض اسنادی ضعف کی وجہ سے کسی حدیث کو متروک اور اس میں مذکور حکم کو باطل قرار دے دیا جائے، جبکہ وہ حکم مُتَلَقّٰی بالقبول ہے، اور اس کے دیگر دلائل موجود ہیں ۔
نیز یہ تحکّم بھی سراسر غلو ہے کہ کسی امام کی مجتہد فیہ تصحیح و تضعیف کو متفق علیہ اور قطعی تصحیح و تضعیف کی طرح کسی دوسرے امام پر مسلط کیاجائے، ا ور اس سے اختلاف کرنے کی وجہ سے ان کو یا ان کے متبعین کو مطعون کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے غلو اور تطرف سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین!
اس موقع پر یہ نکتہ واضح رہے کہ ’’علوم الحدیث‘‘ سے ہماری مراد لغوی معنی کے اعتبارسے علومِ حدیث نہیں ، وہ تو بحرِ ناپیدا کنار ہے، اس میں تو فقہ الحدیث اور علم نقل الحدیث متناً و إسناداً وغیرہ بھی داخل ہیں ۔ ظاہر ہے ان علوم کا موضوع لہ، نقد خبر الآحاد نہیں ہے، بلکہ ہماری مراد وہ علوم ہیں جن کو عرف میں ’ ’علوم الحدیث‘‘ کہا جاتا ہے، ’’علوم الحدیث بالمعنی العام‘‘ میں بہت سے علوم و فنون ایسے ہیں جن کو عرف میں ’’مصطلح الحدیث ــ ‘‘ اور ’’أصول الحدیث ‘‘ بھی کہا جاتا ہے، ’’علوم الحدیث‘‘ سے یہاں یہی علوم وفنون مراد ہیں ۔
یاد رکھیے! ہم نے جو یہ کہا ہے کہ جو امور، اہلِ علم یا جمہور اہلِ علم کے اِجماع سے ثابت ہیں ، یا جن کی حیثیت مسلّمات کی ہے، ان میں خبر واحد کے اصولوں کو نافذ کرنے کی کوشش کرنا غلط ہے، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ ان مسائل کی اصطلاحی صحیح سند نہ ملنے کی وجہ سے ان کا انکار کرنا غلط ہے، یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اگر اُن مسائل کے متعلق کوئی ضعیف روایت آئی ہو تو فنی نقطہ نظر سے اس کا ضعف بیان کرنا بھی درست نہیں ہے، محض فنی لحاظ سے اس کا ضعف بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ، لیکن اس ضعف کو بنیاد بنا کر ان مسلَّمات کو باطل قرار دینا، علومِ حدیث کے استعمال میں حد سے تجاوز اور اِفراط ہے، جو غلط ہے، صرف فنی لحاظ سے کسی روایت کو ضعیف کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ، بلکہ صرف نفس معنی صحیح ہونے کی وجہ سے منکر یا واہی روایت کو صحیح کہنا یا سمجھنا بجائے خود علومِ حدیث کا غلط استعمال ہے، جس کا بیا ن ہم نے مظاہرِ تفریط میں کیا ہے۔ اس کی مزید وضاحت ملاحظہ فرمائیں :
بدیہی سے بدیہی موضوع پر بھی کبھی منکر روایت آجاتی ہے، جیسے: جھوٹ بولنا، قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا زیادہ بڑا گناہ ہے، اس بارے میں حدیث ’’من کذب عليّ متعمّدًا فلیتبوأ مقعدہٗ من النار‘‘ کو اہلِ علم نے متواتر قرار دیاہے، اور بلاشبہ یہ روایت خود ’’ متواترِ اِسنادی‘‘ ہے، اور اس کا مضمون اور معنی تو بہر حال ’’ متواتر بتواترِ طبقہ‘‘ ہے؛ لیکن اس حدیث کے مقدارِ تواتر سے زائد کچھ طرق بھی ہیں ، جن میں سے بعض طرق، ضعیف اور بعض منکر ہیں ، اب اگرکوئی ان خاص طرق کی نکارت کو بیان کرے تو کیا اس کو یہ کہہ کر ملامت کیا جاسکتا ہے کہ یہ تو ’’متواتر‘‘ حدیث ہے، تم اسے ’’منکر‘‘ کیوں کہہ رہے ہو؟ ظاہر ہے کہ ملامت نہیں کیا جاسکتا؛ کیونکہ وہ اس حدیث کو یا معاذ اللہ اس کے مفہوم کو ’’منکر‘‘ نہیں کہہ رہا، بلکہ فنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اس کی بہت سی سندوں میں سے ایک خاص سند کو ضعیف یا منکر کہہ رہا ہے۔ کسی مضمون کے صحیح اور متواتر طرق سے ثابت ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو کو ئی کذا ب یا وضاع بیان نہیں کرے گا۔ اگر کوئی صحیح روایت، منکر طریق سے آئے، یا صحیح اور متواتر حدیث کے کسی خاص طریق میں کوئی منکر اِضافہ ہو تو ایسے طریق اور اضافے کو منکر کہنے میں کیا مانع ہے؟ اور اسے منکر نہ کہنے کا کیا جواز ہے ؟
’’فتح الباري‘‘ میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ’’من کذب علي متعمّدا۔ ۔ ۔ إلخ‘‘ کے طرق کے بارے میں مجموعی طور پر کلام کیا ہے کہ اس کے کتنے طرق صحیح ہیں ؟کتنے حسن، کتنے ضعیف ِمتماسک (یعنی جن کا ضعف شدید نہیں ہے)او رکتنے واہی او رمنکر ہیں ؟ نیز لکھا ہے کہ (۳۳ )صحابہؓ سے یہ روایت، صحیح اور حسن طرق سے ثابت ہے، اور (۵۰) صحابہؓ سے ضعیف اسانید کے ساتھ، جبکہ (۲۰) صحابہؓ سے واہی اسانید سے مروی ہے۔ (فتح الباری: ۱/۲۴۵، ح : ۱۱۰) ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ’’الموضوعات‘‘ کے شروع میں اس حدیث کے ہر طرح کے طرق ذکر کردیے ہیں ۔
اس حدیث کے شانِ ورود کے بارے میں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعات نقل کیے ہیں ، وہ نہ صرف سند کے لحاظ سے ضعیف ہیں ، بلکہ متن کے اعتبار سے بھی منکر ہیں ، اور ان کے مندرجات سے منکرینِ حدیث اور مستشرقین بھی اپنے مقاصد کے لیے استدلال کر سکتے ہیں ؛کیونکہ حفاظتِ حدیث کی تاریخ میں ایک بحث آتی ہے کہ آپ k کے نام پر جھوٹ بولنے کا آغاز کب سے ہوا؟اور کذب علی الرسول کی تاریخ کیا ہے ؟ مستشرقین کی کوشش ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو قدیم سے قدیم ترثابت کیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس نوعیت کا جھوٹ شروع ہوگیا تھا، اوردلیل میں اسی حدیث ’’من کذب عليّ متعمّدا۔۔۔ إلخ‘‘ کا حوالہ دیتے ہیں کہ اگر جھوٹ کا کوئی واقعہ نہیں ہوا تو یہ بات کیوں کہی گئی؟! یہ بالکل جاہلانہ اورمعاندانہ بات ہے، اس زمانے میں کون جھوٹ بولتا تھا ؟ ’’خیر الناس قرني، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، ثم یفشو الکذب‘‘، الحدیث۔ (صحیح البخاری: ۲۶۵۲)
قرآن کریم میں ارشاد ہے:
’’لَىِٕنْ اَشْرَکْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ وَلَتَکُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ ‘‘ (الزمر:۶۵)
’’اے عام مخاطب! اگر تو شرک کرے گا تو تیرا کیا کرایا کام غارت ہوجائے گا اور تو خسارہ میں پڑے گا۔‘‘
’’وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِیْلِ لَاَخَذْنَا مِنْہُ بِالْیَمِیْنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْہُ الْوَتِیْنَ‘‘ (الحاقۃ:۴۴، ۴۶)
’’ اور اگر یہ ہمارے ذمہ کچھ باتیں لگادیتے تو ہم اُن کا داہنا ہاتھ پکڑتے، پھر ان کی رگ کاٹ دیتے۔‘‘
یہ آیات کیوں نازل ہوئیں ؟کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا تھا؟ یا ایسا ہونے کاکوئی شائبہ یا امکان بھی تھا ؟!
یہ تو ان معاندین کی ایک عقلی اُپج تھی، البتہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو واقعہ بیان کیاہے، وہ بالکل منکر ہے، جھوٹ کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے جھوٹی روایت لے آئے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ’’الصارم المسلول‘‘ میں اس واقعہ کو اس طرح نقل کیا ہے کہ گویا ا س کو صحیح سمجھ رہے ہیں ، جس پر حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے نکیر کرتے ہوئے ’’سیر أعلام النبلاء‘‘ میں لکھا ہے: ’’ تمّ علیہ الوھم في ذلک‘‘ (۷/۳۷۴) (یعنی ابن تیمیہؒ کو اس واقعہ کے نقل کرنے میں وہم ہوا ہے)اور ’’میزان الاعتدال‘‘ (ج: ۲ ص:۲۹۳)میں لکھا ہے : ’’ورواہ کلہ صاحب الصارم المسلول، وصحّحہ، ولم یصحّ بوجہ۔‘‘ (صاحبِ ’’الصارم المسلول‘‘ نے اس روایت کو مکمل نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا ہے، حالانکہ یہ روایت کسی طور صحیح نہیں ہے)۔
حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ’’التلخیص الحبیر‘‘ میں اس مقام پر کچھ خلط ہوا ہے کہ منکر حصہ پرمشتمل روایت کو ایسے شاہد کی بنیاد پرحسن کہہ دیا ہے، جس میں وہ منکر حصہ سرے سے نہیں ہے۔ بہرحال یہ روایت(یعنی عہدِ رسالت میں کذب علی النبي صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع ہونا) بالکل منکر ہے، اور سند کے لحاظ سے بھی ثابت نہیں ۔ ’’لمحات من تاریخ السنۃ وعلوم الحدیث‘‘ للشیخ عبدالفتاح أبوغدۃ رحمہ اللہ (ص:۵۶- ۶۵)میں اس کی تفصیل دیکھی جاسکتی ہے۔
مستشرقین وغیرہ کا مقصد یہ ہے کہ دورِ رسالت میں جھوٹ کا وجود ثابت کریں ، تاکہ یہ کہہ سکیں کہ سب سے زیادہ حدیثیں کون بیان کرتا تھا؟ اس طرح سیدنا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ جیسے حافظ الصحابہؓ، اور امامِ صدق و اتقان کو مطعون کرنا چاہتے ہیں ۔ رضي اللہ تعالیٰ عن الصحابۃ وأرضاہم، وأبعد الطاعنین فیھم وأخزاہم۔
ہماری زیرِ تصنیف کتاب ’’إنعام النظر‘‘ میں ایک عنو ان ہے : ’’الوضع في الموضوعات‘‘ یعنی ’’موضوعات کے بارے میں وضع، اور کذابین کے بارے میں جھوٹ۔‘‘ اس کی بہت سی صورتیں ہیں ، مثلاً: یوں کہہ دیا کہ فلاں نے اتنے لاکھ احادیث وضع کیں ! سوال یہ ہے کہ کیااس میں اتنی صلاحیت اور عقل تھی کہ اتنی روایات وضع کر سکتا؟
مختلف کذّابین کے بارے میں جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں ، ان میں موضوعات اور من گھڑت باتیں بھی ہیں ، جیسے: ’’رتن ہندی‘‘ کے بارے میں بہت سی احادیث وضع کی گئی ہیں ، جوخود اس نے بیان نہیں کیں ۔ ایک کتاب ہے: ’’الرتنیات‘‘، یعنی وہ روایات جو رتن ہندی نے روایت کی ہیں ، اب وہ تو ہندی شخص تھا، اس میں اتنا سلیقہ کہاں تھا کہ عربی میں اتنی روایتیں گھڑ لیتا؟ اما م ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ’’میزان الاعتدال‘‘ میں لکھا ہے: ’’ ومع کونہٖ دجالا کذّابا فقد کذبوا علیہ جملۃ کبیرۃ من أسمج الکذب والمحال‘‘ (۲/۴۵) (رتن ہندی کے خود کذاب ودجال ہونے کے باوجودبعض لوگوں نے اس پرایسی روایات گڑھ لی ہیں ، جو انتہا درجہ جھوٹی اور محال ہیں )۔ اسے کہتے ہیں : ’’الوضع في الموضوعات‘‘، (یعنی موضوعات کے متعلق من گھڑت روایتیں !)، یہ بھی جائز نہیں ؛کیونکہ کذّاب پر بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، لہٰذا اگرکوئی شخص کسی کذّاب کے واسطے سے ہی حدیث وضع کر ے تو یہ دروغ اور غَرر کا مجموعہ ہوگا۔
حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ا ور مولانا عبدا لصمد صارم رحمۃ اللہ علیہ نے ’’رتن ہندی‘‘ کو صحابیؓ لکھ دیا ہے۔ صارم صاحب کا مطالعہ فی الجملہ اچھا تھا، اس لیے بہت سی کتابیں بھی لکھیں ؛ لیکن علمِ روایت سے انہیں خاص مناسبت حاصل نہیں تھی، اوراِتقان بھی کم تھا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، عقل اونچی تھی، فکر بلند تھی، سلیقہ تھا، مطالعہ فی الجملہ وسیع تھا، انہیں بہت سے کمالات حاصل تھے، اس لیے ان کے قلم سے بہت اچھی اچھی کتابیں سامنے آئیں : ’’ہندوستان میں نظامِ تعلیم و تربیت‘‘، ’’ تدوینِ حدیث‘‘ اور ’’تدوینِ قرآن‘‘ بعض پہلؤوں سے اچھی کتابیں ہیں ۔ ’’النبي الخاتم‘‘ مختصر ہونے کے باوجود ایک شاہ کار ہے، لیکن انہیں علمِ روایت سے خاص مناسبت حاصل نہیں تھی، جہاں خالص نقل چاہیے، وہاں عقل بہرحال کام نہیں آسکتی۔ ’’علم النقد والنقل‘‘ کو سمجھنے کے لیے روایت کی اصطلاحات و زبان سے واقفیت ضروری ہے۔ اگریہاں بھی عقل استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو وہی حالت ہوگی جو بہت پہلے علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ ( شارحِ بخاری) کی ہوئی، چنانچہ ’’باب بدء الوحي‘‘ کے آخرمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے قول ’’رواہ صالح بن کیسان ویونس و معمر عن الزھري‘‘ کی شرح میں علامہ کرمانیؒ نے مختلف احتمالات بیان کیے اور لکھا ہے: ’’وإن کان الظاہر اتحاد الإسناد‘‘ (۱/۶۸) حافظ رحمۃ اللہ علیہ کو کہنا پڑا:
’’ھٰذا الظاہر کاف لمن شمّ أدنی رائحۃ من علم الإسناد، و الاحتمالات العقلیۃ المجرّدۃ لامدخل لھا في ھذا الفن۔‘‘
’’علمِ اسناد ‘‘ سے ادنیٰ مناسبت کے حامل کے لیے یہ ظاہر کافی ہے، درحقیقت محض عقلی احتمالات کا اس فن میں کوئی کردار نہیں ۔‘‘
اسی طرح علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے آدمی ہیں ، لیکن منقولات میں ان سے بھی تسامح ہوتا رہتا ہے، یہ صرف حضرت مولانا مناظراحسن گیلا نی رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں ، بہت سے لوگو ں سے ایسی لغزشیں ہوئی ہیں ۔
بہرحال اصولی طور پر روایت کے فن میں احتمالاتِ عقلیہ مجردہ کو دخل نہیں دینا چاہیے، جہاں خالص نقل کی ضرورت ہو، وہاں نقل کے اسرارورموز سے آشنائی ضروری ہے، صرف عقل کی دوڑ کام نہیں آئے گی۔ اس میں شک نہیں کہ نقل کے لیے بھی عقل چاہیے اور عقل کے بغیر نقل کا حق ادا نہیں ہوسکتا۔ کہا جاتا ہے: ’’یک من علم را دہ من عقل باید‘‘ (ایک من علم کے لیے دس من عقل درکار ہوتی ہے)، اسی لیے ہم فنی اعتبار سے تفقّہ پر زور دیتے ہیں ، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ خاص نقل کے مقام پر محض عقل استعمال کرنا بجائے خود غلط ہے، روزمرہ کی مثال دیکھ لیں ، مثلاً: کوئی شخص پوچھے: کمرے میں فلاں شخص موجود ہے یانہیں ؟ اب صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ کمرے میں دیکھا جائے اور اس کے بعد بات کی جائے۔ اگر کوئی شخص وہیں بیٹھے بیٹھے محض احتمالات بیان کرنا شروع کر دے کہ اس وقت چوں کہ فلاں شخص یہاں کام کرتا ہے، اس لیے اس کا ہونا ممکن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ان عقلی احتمالات سے کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا۔
بہرکیف ’’ رتن ہندی‘‘ کا معاملہ خالص نقل سے تعلق رکھتا ہے؛ لیکن مولانا گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عقلی طور پر حل کرنے کی کوشش کی ہے، کسی ماہنامہ میں ان کا یہ مضمون چھپا، اس کے بعد علیحدہ رسالے کی صورت میں ’’ایک ہندوستانی صحابی ‘‘ کے نام سے شائع ہواہے! ’’الإصابۃ‘‘ وغیرہ میں ’’رتن ہندی‘‘ کی صحابیت کے خلاف واضح دلائل موجود ہیں ، لیکن مولانا کو تنبُّہ نہیں ہوا، اس کا سبب صرف فنی اصطلاحات اور تعبیرات کے ساتھ قلتِ انس ہے اور کچھ نہیں ، بس اسی وجہ سے ’’رتن‘‘ کا صحابی نہ ہونا جو ایک متفق علیہ مسئلہ تھا، وہ ان کی نظر میں مختلف فیہ ہوگیا !
خیر یہ حدیث ’’من کذب علي متعمّدا۔ ۔ ۔ إلخ‘‘ متواتر ہے؛ لیکن اس کے منکر طرق کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ جھوٹ بولنا تو بدیہی طور پر حرا م ہے، اور اس روایت میں بھی یہی آیا ہے، نیز مسلّمات اور ضروریات میں سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، لہٰذا یہ روایت، صحیح ہے ! بتائیے کیا ایسا کہنا درست ہوگا ؟ ظاہر ہے کہ یہ کہنا غلط ہے اور علومِ حدیث کی غلط تطبیق ہے۔ یہ روایت بجائے خود فنی اعتبار سے منکر ہے، لہٰذا اسے منکر ہی کہا جائے گا، اور قدرِ مشترک سے زائد جتنی باتیں صرف ان منکر طرق میں موجود ہیں ، وہ منکر اور متروک ہی ہوں گی۔
مظاہرِ افراط میں سے صرف دو مظاہر مزید ذکر کرتے ہیں ، ویسے بھی اس موقع پر کسی بھی موضوع میں استقصاء مقصد نہیں ہے، بلکہ بعض ضروری باتیں ذکر کرنا مقصود ہے۔
علومِ حدیث کی میراث سے استفادے کے تین طریقے ہیں :
1-محقّقانہ 2-مقلّدانہ 3-جاہلانہ۔
بعض عقل پرست لوگ، جنہیں ’’علوم الإسناد‘‘ کی شُدبُد ہی نہیں ، علومِ حدیث کے قواعد سے استفادے کی جرأت کرتے ہیں ، ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا استفادہ ’’جاہلانہ‘‘ ہی ہوگا اور تحریف اور اِفساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا! ایسے لوگوں کے لیے جائز ہی نہیں کہ علومِ حدیث سے براہِ راست استفادہ کریں ، بلکہ انہیں تواہلِ علم کی تقلید کرنی چاہیے۔ اسی طرح جو ’’ مقلّدانہ ‘‘ استعمال جانتا ہو، اس کے لیے اپنی حدودسے بڑھ کر ’’ محقّقانہ ‘‘ استعمال غلط ہوگا۔
مقلّدانہ طور پر علومِ حدیث سے استفادے کا سلیقہ سیکھنے کے لیے بھی بہت محنت کی ضرورت ہے، ہمارے ہاں طلبہ دو تین سال ’’تدریب في علوم الحدیث‘‘ میں لگاتے ہیں ، ان تین سالوں میں بہت سے طلبہ کو علومِ حدیث سے مقلّدانہ استفادے کا صحیح سلیقہ بھی نہیں آتا؛ کیونکہ ذی استعداد، باصلاحیت اور نبیہ طالب علم کو بھی مقلّدانہ استفادے کا ملکہ حاصل کرنے کے لیے کم از کم چار پانچ سالوں کی ضرورت ہے۔ اب اگرکسی نے مقلّدانہ استفادے کا طریقہ بھی نہ سیکھا ہو اور فن میں دخل اندازی اس طور پر کرنے لگے کہ گویا وہ محقّقِ فن ہے، تو نتیجے میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اسی طرح اگرکسی نے مقلّدانہ استعمال تو سیکھ لیا، لیکن ان علوم کا استعمال محقّقانہ کر رہا ہو، تو یہ بھی علو مِ حدیث کا غلط اور اِفراط پر مبنی استعمال ہے، جوناجائز ہے۔
کسی کے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ یہ طرزِ عمل کیوں ناجائز ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ علومِ حدیث کے بہت سے قواعد، حساب کے قواعد کی طرح بالکل دو ٹوک نہیں ہیں کہ دو اوردو چارکی طرح ہوں ، کیا دو اور دو چار کی طرح حدیثِ حسن، شاذ اور منکر کی کوئی تعریف ہے؟ کس راوی کو ’’ منکر الحدیث‘‘ کہنا ہے؟ کیا اس کا کوئی متعین اور واضح معیار ہے کہ ہر ایک اس کو سمجھ لے؟ نیز بہت سے امور کا معیار تو موجود ہے، لیکن اتنا دو ٹوک اور واضح نہیں ہے کہ غیر اہلِ فن بھی اس کی تمیز کر سکیں ، ناسمجھ آدمی‘ اہلِ فن سے لڑتا رہے گا کہ کہیں کچھ کہہ دیتے ہیں اور کہیں کچھ، جبکہ اہلِ فن سے لڑنا بے ذوقی کی دلیل ہے۔
اہلِ فن، ’’اشباہ و نظائر‘‘ اور ’’فروق‘‘ سے آگاہ ہوتے ہیں ، اوربہت سے امور بظاہر ایک جیسے نظرا ٓتے ہیں ؛لیکن حقیقت میں ان میں دقیق فرق ہوتا ہے، جسے اہلِ فن سمجھتے ہیں ۔
اہلِ فن ایک ہی ثقہ راوی کی ’’ زیادت‘‘ کہیں قبول کر لیتے ہیں اور کہیں اسی کی ’’زیادت‘‘ کو شاذ کہہ دیتے ہیں ۔ یہ معمّہ اہلِ فن آپس میں حل کر سکتے ہیں ، غیر اہلِ فن اسے حل نہیں کرسکتے؛کیونکہ اہلِ فن کو ’’فروق‘‘ معلوم ہوتے ہیں اور غیر اہلِ فن کی نظر ان امور سے قاصر ہوتی ہے، اس بنا پر غیر اہلِ فن کے لیے اہلِ فن کی تقلید کے علاوہ سلامتی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور ہر فن میں وہی ماہر ہوتا ہے جو اس فن کے مشتبہات میں وجوہ ِفرق کا اِدراک کرسکے، غیر اہلِ فن کہاں ان دقائق تک رسائی حاصل کرسکتا ہے؟! مثلاً: ایک ہی معیار کے دو ثقہ راویوں میں سے ایک کی زیادت‘ حسن قرار پاتی ہے او ردوسرے کی ضعیف۔ غیر اہلِ فن کو یہ فرق سمجھانامحال ہے، اہلِ فن ہی ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں ۔
اگر فن سے ناواقف لوگ‘ فن کا محقّقانہ استعمال وتطبیق کریں گے تو منکر کو معروف اور معروف کو منکر بنائیں گے، شاذ کو محفوظ او رمحفوظ کو شاذ بنائیں گے۔ یہ اس غلط استعمال کا کم تر خسارہ ہے، اس لیے جس میں صر ف مقلّدانہ استعمال کی صلاحیت ہو تو اسے محققانہ استعمال کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، ایسی کوشش حد سے تجاوز اور علومِ حدیث کا غلط استعمال ہو گا۔
علومِ حدیث کے استعمال وتطبیق کے لیے ادب او رذوق ہونا بھی ازحد ضروری ہے، جس شخص میں ادب، ذوق اورفنی بصیرت نہ ہو، اسے علومِ حدیث کے استعمال کا حق نہیں پہنچتا۔ اد ب اور ذوق نہ ہونے کے جو بھیانک نتائج ہیں ، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسا شخص، عوام ( جن کا فہم، علل اور جرح وتعدیل کے حقائق اور دقائق کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے، ان) کے سامنے بھی فنی امور بیان کرنے لگتا ہے، یہ بے ذوقی کی علامت ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اہلِ مکہ کے نام اپنے خط میں لکھا تھا :
’’وربّما کان في الحدیث ما تثبت صحۃ الحدیث منہ، إذا کان یخفی ذلک علي، فربما ترکت الحدیث إذا لم أفقہہ، وربما کتبتُہ و بیّنتُہ، وربما لم أقف علیہ، وربما أتوقف عن مثل ہٰذا؛ لأنہٗ ضررٌ علی العامّۃ أن یکشف لہم کل ماکان من ہٰذا الباب، فیما مضی من عیوب الحدیث؛ لأن علم العامۃ یقصر عن مثل ہٰذا۔ ‘‘
یعنی ’’ممکن ہے کہ کسی حدیث میں ثبوتِ صحت کی علامات موجود ہوں ،لیکن مجھ سے مخفی رہ گئی ہوں ، تو ایسے موقع پر کبھی میں کسی حدیث کو تو سمجھ نہ پاؤں تو اسے ترک کردیتا ہوں ، کبھی اسے کتاب میں لکھ کر اس کااِسنادی حال (علت، وغیرہ) بھی بیان کردیتا ہوں ، کبھی میں خود اس کے حال سے واقف نہیں ہوتا، اور کبھی حدیث کے متعلق علل کو کتاب میں درج کرنے سے توقف اختیار کرلیتا ہوں ؛ کیوں کہ عوام کے سامنے کسی حدیث کی علتوں سے متعلق تمام فنی امور کو ظاہر کرنا نقصان دہ ثابت ہوتا ہے؛ اس لیے کہ ان کا علم ان امور کے اِدراک سے قاصر ہوتا ہے۔ ‘‘
باوجودیکہ یہ کتاب‘ علماء کے لیے لکھی گئی تھی؛ لیکن پھر بھی امام ابوداود رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں احادیث کی بہت سی علل اس لیے بیان نہیں کیں کہ وہ عام لوگوں کے فہم سے بالاتر ہیں ۔
جن لوگو ں کے دلوں میں مرض ہوگا، وہ تو جان بوجھ کر ایسا کام کریں گے ؛تاکہ لوگوں کے دلوں سے علومِ حدیث سے متعلق اعتماد اٹھ جائے۔ ایک شیعہ کی کتاب ہے: ’’استقصاء الإفحام واستیفاء الانتقام‘‘، یہ کتاب میں نے حضرت الاستاذ مولانا محمد عبدالرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیکھی تھی، اس کامصنف مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ہے، اور ’’الرفع والتکمیل في الجرح والتعدیل‘‘ (ص: ۱۷۳) میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس شخص نے جرح و تعدیل کا اتنا غلط استعمال کیا ہے کہ اللہ کی پناہ! اس کے بقول: ’’امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کا کوئی اعتبار نہیں ، نعوذ باللہ؛ کیوں کہ امام بخاری کے بارے میں فلاں فلاں جرحیں ہیں !‘‘ حالاں کہ یہ جرحیں خود مجروح اور باطل ہیں ۔ طُرفہ یہ ہے کہ اس شخص نے جن لوگوں کے اقوال کی بنیاد پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پر جرح کی ہے، بعد میں جب اسے انہی لوگوں پر جرح کی ضرورت پڑی تو ان پر بھی جرحوں کا انبار لگا دیااور استدلال میں خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جرح کو بھی نقل کر دیا، یہ بے شرمی کی انتہا ہے!!
یہ انتہا درجہ کی بے ذوقی اور بے ادبی ہے کہ عوام کے سامنے ’’ جرحِ مجروح‘‘ اور ’’اعلالِ معلول‘‘ کی بحثیں رکھ دیں ۔
اعلالِ معلول: یعنی وہ اعلال جو معلول ہے، یعنی کسی محدث نے کہا کہ یہ معلول ہے، حالانکہ وہ معلول نہیں ہے، بلکہ اسے معلول کہنا معلول ہے، تویہ اعلالِ معلول ہوا۔
جرحِ معلول: یعنی کسی نے جرح کی، حالانکہ وہ جرح خود غلط ہے، شرعی جرح نہیں ہے، تو یہ جرح خود مجروح ہوئی۔
بے ذوقی اور بے ادبی یہ ہے کہ عوام کے سامنے ’’جرحِ مجروح‘‘ او ر ’’اعلالِ معلول ‘‘ جیسی بحثیں رکھ دی جائیں ، ایسے افراد کے لیے علومِ حدیث میں دخل دینا ناجائز ہے، بلکہ عوام کے سامنے ’’ جرحِ مجروح‘‘ اور ’’اعلالِ معلول‘‘ کی بحثیں رکھنا تو ناجائز ہے ہی، ان کے سامنے تووہ صحیح امور بھی پیش نہ کرنے چاہئیں جودقیق ہیں ، جیسے ماقبل میں امام ابوداود رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت میں گزرا ہے۔ بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں ، اور دقیق باتیں تو الگ رہیں ، وہ تو عوام کے سامنے خرافات پیش کرتے ہیں ۔ ذیل میں اس حوالے سے چند واقعات ملاحظہ کیجیے:
ایک مجلس میں علماء، ضعیف روایت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور وہاں ایک عامی بھی موجود تھے، جوشاید ان علماء سے بے تکلف تھے، اس لیے انہوں نے ضعیف حدیث کے بارے میں اپنا خیال پیش کرتے ہوئے کہا: ’’ میرے خیال میں جہاں تک صحابہ کرام s کی بات ہے تو ان کا ایمان بہت مضبوط تھا، ان کے لیے ضعیف حدیث نہیں چل سکتی تھی، ہم جیسے کمزور ایمان والوں کے لیے توضعیف حدیث بھی چل جائے گی!!‘‘ یہ واقعہ مولانا لطیف الرحمٰن بہرائچی نے ’’تحقیق المقال‘‘ (ص: ۴۲) میں نقل کیا ہے۔ اب بتائیے! ایسے عوام، علمِ علل کے دقائق کو کیاسمجھیں گے ؟!
میں جب ’’ریاض‘‘ سے تازہ تاز ہ ’’بنگلہ دیش‘‘ واپس آیا تو کافی عرصہ بعد اپنے گاؤں ’’کملاء‘‘ میں رہنے کا موقع ملا، ایک دفعہ مسجد میں ایک صاحب بیان کر رہے تھے اور موضوع روایات بیان کر رہے تھے، ان کے فارغ ہونے کے بعد مجھے خیال ہوا کہ تنبیہ کر دینی چاہیے کہ یہ روایات درست نہیں ہیں ، لیکن ہمارے ان بھائی کو اچھا نہ لگا، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ : ’’ آپ مجھے کیاسمجھا رہے ہیں ؟مجھے معلوم ہے کہ حدیث کی قسمیں ہوتی ہیں : حسن، اوراحسن !‘‘
ایک نواب صاحب، ایک مجلس میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک طویل موضوع روایت بیان کررہے تھے، شایدکتاب کے ترجمے کا مطالعہ کیا ہوگا۔ مجھے اندازہ ہوگیا کہ یہ منکر اور موضوع روایت ہے، اور ابنِ کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ: ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد کچھ لکھا نہیں ہے؟ کہنے لگے: ’’ موضوع لکھاہے تو کیا ہوا ؟! حدیث ہی تو ہے!‘‘ ایسے لوگوں کو آپ علومِ حدیث کے اصول کیسے سمجھائیں گے ؟!
حافظ زین الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک استفتاء آیا کہ یہ حدیث کیسی ہے ؟ انہوں نے بتایا کہ یہ موضوع ہے۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ: ’’ یہ تم کس سے فتوی لے آئے ہو؟ کون کہتا ہے کہ یہ روایت، صحیح نہیں ہے، میرے پاس حدیث کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے‘‘ اور پھر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کی ’’کتاب الموضوعات‘‘ سے روایت نکال کر دکھادی۔ (فتح المغیث:۱/۲۹۴)
شیخ محمد زاہدکوثری رحمۃ اللہ علیہ نے دمشق کی ایک مسجد میں خطیب صاحب کا بیان سنا، وہ ایک موضوع روایت بیان کرنے کے بعد بھرپور اعتمادکے ساتھ حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہے تھے: ’’رواہ ابن الجوزي في الموضوعات!!‘‘ یعنی یہ روایت میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا، بلکہ کتابوں میں یہ روایت موجود ہے، ابن جوزیؒ کی ’’کتاب الموضوعات‘‘ میں ہے۔ (مقالات الکوثری، ص:۲۴، البتہ اس کتاب میں شہر کا نام مبہم رکھا گیا، شہر کی تعیین مجھے شیخ عبد الفتاح ابو غدّہ رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوئی) ایسے عوام اور جہلاء کو آپ جرح وعلل کیسے سمجھائیں گے؟!
الغرض علومِ حدیث کا صحیح اور معتدل استعما ل سیکھنے کی ضرورت ہے اور یہ استعمال بغیر تفقّہ کے نا ممکن ہے۔ علومِ حدیث کا معتدل استعمال وتطبیق وہی کرسکتا ہے جس نے اس فن میں تفقّہ حاصل کیا ہو اور فقہاء في الفن کی صحبت اُٹھائی ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین!