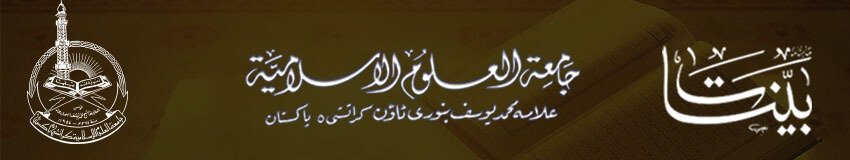
علومِ حدیث، امتِ مسلمہ کی درخشاں علمی تاریخ کا گلِ سرسبد ہیں، محدثین نے ان علوم پر جو محنتیں صرف کی ہیں، ان کی بدولت اسباب کے درجے میں یہ علوم‘ ذخیرۂ حدیث کی حفاظت کا ذریعہ ثابت ہوئے، یوں حفاظتِ قرآنی کے ضمن میں حفاظتِ حدیث کا خدائی وعدہ پورا ہوا۔ محدثین کی کاوشیں بلاشبہ عقل ونقل کے پیمانوں پر پورا اُترتی ہیں، اور مسلم عقلیت کی تشکیل میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان علوم کا تعلق محض ذخیرۂ حدیث سے نہیں، بلکہ نقل وروایت کے ہر میدان میں یہ علوم، کسوٹی کی حیثیت رکھتے اور اصولِ نقل فراہم کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں ذرائعِ ابلاغ سے وابستہ طبقات اگر ان اصولِ نقل کو برتنے لگیں تو بہت سے ’’حقائق اور انکشافات‘‘ منظرِ عام پر آنے سے قبل ہی اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ عام لوگ روزمرہ کی ’’سنسنی پھیلاتی خبروں‘‘ کی چھان پھٹک میں انہیں برتنا شروع کردیں توانسانی ذہنوں میں آئے بہت سے بھونچال، تباہی پھیلانے سے پہلے ہی دم توڑ جائیں، بلاشبہ یہ اصول ہر دم تازہ دم اور سبک خرام ہیں اور رہیں گے، ان شاء اللہ!
آمدم بر سرِمطلب! علومِ حدیث کے مفید اور ثمر آورہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ بڑھیا سے بڑھیا شے کا ناروا استعمال اس کی افادیت کو ٹھیس پہنچاتا اور افادیت کی بجائے اُلٹا نقصان کا باعث بن جایا کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہی حال علومِ حدیث کا بھی ہے، ناپختہ فکری کے ساتھ علمیت کا سودا اگر دماغ میں سما جائے تو انسان‘ مفید غذا کو زہرناک بناڈالتا ہے، اور علمی اصولوں کوہی بنیاد بنا کر علمی روایت کو ڈھاتا چلا جاتا ہے، طُرفہ یہ کہ ایسی ذہنیتیں اپنے ناقص کاموں کو علمی کارنامہ باور کراتی ہیں اور خود پر نازاں بھی رہتی ہیں: ’’ ببیں تفاوتِ رہ از کجا است تا بکجا!‘‘۔
علومِ حدیث کی تطبیق میں اِفراط ووتفریط کے جو مظاہر‘ معاصر علمی اُفق پر دکھائی دیتے ہیں، اور ان کے نتیجے میں سلف واکابر کے تئیں بے اعتمادی کی جیسی فضا بن رہی ہے، سنجیدہ اہلِ علم اس تکلیف دہ منظر نامے کا درد قلب وجگر میں محسوس کرتے اور اپنے مستفیدین ومتعلقین کو اس سے باخبر رکھنے اور درست راہ پر گامزن رہنے کی تلقین کرتے رہتے ہیں۔
پیشِ نظر مضمون اسی نوعیت کے ایک علمی محاضرے کی تحریری صورت گری ہے، محاضرِ محترم حضرت مولانا محمد عبد المالک صاحب مدظلہم (رئیس شعبہ ’’تدریب في علوم الحدیث‘‘ مرکز الدعوۃ الإسلامیۃ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش) علومِ حدیث وفقہ اسلامی کے طلبہ کے لیے موجودہ دور کی مغتنم شخصیت ہیں، انہیں یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں متعدد نابغۂ عصر ہستیوں سے استفادہ کا زرّیں موقع عنایت فرمایا۔ جامعہ علومِ اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن سے درسِ نظامی کی تکمیل کے بعدانہوں نے دو برس شعبہ تخصصِ علومِ حدیث میں برصغیر کے نامور محقق عالم حضرت مولانا محمد عبد الرشید نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی تربیت کے سائے تلے گزارے، اس دوران نامور مناظر ومحقق عالم مولانا امین صفدر اوکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی مستفید ہوتے رہے، بعد ازاں جامعہ دارالعلوم کراچی کے شعبہ تخصص فی الافتاء میں ڈھائی برس تک محدثِ فقیہ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہم سے فیض یاب ہوتے رہے، اور پھر عالمِ عربی کے بلند پایہ محقق ومحدث شیخ عبد الفتاح ابوغدہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامنِ فیض سے وابستہ ہوکر لگ بھگ دوسال تک ان کے متفرق علمی امور میں معاونت کرتے اور ان سے مستفیض ہوتے رہے، اس دوران بیس سے زائد کتب ورسائل کی تالیف وتحقیق میں ان کی رفاقت کا شرف حاصل رہا۔ مذکورہ بالا اہلِ علم میں سے ہر ایک اس پائے کے ہیں کہ محض کسی ایک سے انتساب واستفادہ بھی سرمایۂ افتخار ہے، پھر جنہیں ان سبہی سے مستفید ہونے کا موقع ملتا رہا ہو، ان کی سعادت مندی میں کیا شبہ ہوسکتا ہے؟!
کچھ عرصہ قبل مولانا مدظلہم کی کتاب ’’محاضرات علوم الحدیث‘‘ (شائع شدہ از مرکز الدعوۃ الإسلامیۃ، ڈھاکہ، بنگلہ دیش) طبع ہوئی، اور سال بھر میں اس کے دو ایڈیشن شائع ہوئے۔ اس کتاب میں ’’مقدمۃ ابن الصلاح‘‘ کی ابتدائی بارہ انواع سے متعلق ان کے محاضرے قلم بند کرکے ترتیب دیے گئے ہیں۔ پیشِ نظر مضمون کا انتخاب اسی کتاب سے کیا گیا ہے۔ مولانا مدظلہم نے اس محاضرہ میں علومِ حدیث کی تطبیق میں افراط وتفریط کے مظاہر اور ان کے نتائج کے تعلق سے پُرمغز گفتگو فرمائی ہے، اور اس ضمن میں بہت سے علمی دقائق، مفید نکات، پرلطف چٹکلے اوردلچسپ واقعات بھی آگئے ہیں، علومِ حدیث کے طلبہ کے لیے یہ سب کچھ حد درجہ مفید ہے۔ چونکہ وطنِ عزیز میںتاحال اس کتاب کی اشاعت نہیں ہوسکی، اور کتاب، عام طلبہ واہلِ علم کی دسترس میں نہیں، اس بنا پر بندہ نے اس محاضرے کا انتخاب کرکے کسی معنوی تغیر کے بغیر قدرے تلخیص کی، اور لفظی و تعبیری نوک پلک سنوارکر اس میں تحریری رنگ بھرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے، نیزحسبِ ضرورت عبارات کا ترجمہ اور ہلکی پھلکی تخریج کی ہے، اور بعد ازاں اطمینان کے لیے اسے حضرت مولانا مدظلہم کی خدمت میں پیش کرکے اُن کی اجازت سے شائع کیا جارہا ہے۔ اُمید ہے کہ یہ مضمون، حدیث کے طلبہ واہلِ علم کے لیے علومِ حدیث کی تطبیق کے تعلق سے خضرِ راہ ثابت ہوگا، اوران کے قلوب میں اصل کتاب کے مطالعہ کا اشتیاق بڑھنے کا ذریعہ ثابت ہوگا، رہا کتاب کے حصول کا معاملہ توسچ ہے کہ ’’جویندہ یابندہ‘‘۔ (از مرتب)
علومِ حدیث سے متعلق مباحث میں سے ایک اہم بحث ’’وجوہ الإفراط والتفریط في استخدام علوم الحدیث‘‘ (یعنی علومِ حدیث کی تطبیق میں افراط وتفریط کے مظاہر)ہے۔
اِفراط: یعنی حدود کا خیال نہ رکھنا، اپنے مقام سے تجاوز کرنا، اوربے موقع استعمال کرنا۔
تفریط : یعنی کسی شے کا حق ادا نہ کرنا، اور جہاں اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، وہاںخیال نہ رکھنا۔
افراط و تفریط ہر چیز میں مذموم ہے، طلبہ کرام کے لیے علومِ حدیث میں جن مباحث کی تدریب ضروری ہے، ان میںسے ایک اہم بحث یہ بھی ہے کہ وہ علومِ حدیث کامعتدل اور صحیح تطبیق واستعمال سیکھیں۔ ذیل میں اس حوالے سے چند اہم نکات پیش کیے جائیں گے۔
بہت سے لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ علم صرف نمونہ، برکت یا آثارِ قدیمہ کی طرح ایک یاد گار کی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محض اصطلاحی علم ہے، جس کو ایک مرتبہ نظر سے گزارلینا چاہیے، یا چوں کہ اس کا تعلق حدیث سے ہے، اس لیے برکت کی نیت سے پڑھ لینا چاہیے، یا چونکہ ہمارے بزرگ اسے پڑھتے پڑھاتے آئے ہیں، اس لیے گویا آثارِ قدیمہ کی مانند اس کا محض تذکرہ ہوجائے تو کافی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب دل میںیہ تصور ہوگا تو عملاً کیا حال ہو گا؟! چنانچہ تطبیقی میدا ن میں آپ کو اس علم کا نام بھی نظر نہیں آئے گا، یا صرف اس قدر کہ برکت کا حصول ہوجائے، إلا ماشاء اللہ۔
علومِ حدیث کی تطبیق کے پانچ بڑے میدا ن ہیں :
1- احادیثِ ضعیفہ 2- احادیثِ موضوعہ
3- مختلف فیہا مسائل 4- کتبِ حدیث کا درس اور شروحِ حدیث کا مطالعہ۔
5- منکرینِ حدیث اور مستشرقین کا رد۔
اس اہم میدان میں علومِ حدیث کے اصولوں کو کام میں لانا چاہیے، لیکن بعض طلبہ ومدرسین اوربہت سے واعظین و خطباء کے حالات سے یہ شبہ ہوتا ہے کہ گویا وہ یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں کہ غلطی سے بھی انہیں ہاتھ نہیں لگانا، بلاہچکچاہٹ موضوع اور منکر روایات بیان کی جاتی ہیں، اور کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، اگر متوجہ کیا جائے تو اس بارے میںان کے مختلف بہانے ہوتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہی حیلے بہانے ان کے اصول ہیں۔
1- ایک بہانہ یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابوںمیں کوئی حدیث مل جائے تو اسے لے لینا چاہیے، مثلاً: کوئی حدیث ’’إحیاء علوم الدین‘‘ میں مل جائے یا تصوف کی کسی اور کتاب میں مل جائے تواس کی تحقیق کی ضرورت نہیں، حالانکہ اصولی طور پر عصرِ روایت کے بعد کی معلّق روایات (جن روایات کی سند کی ابتدا سے راوی ساقط ہوں) کے حوالے تلاش کرنا، اور پھر ان کی سندوں کی تحقیق کرنا بالاجماع فرض ہے، مرسل روایات کو قبول کرنے والوں کے نزدیک بھی یہ عمل ضروی ہے۔ (ملاحظہ فرمائیے: ظفر الأماني، ص:۳۴۱ ـ۳۴۴؛ الأجوبۃ الفاضلۃ، ص:۳۱ ـ۳۴، المدخل إلی علوم الحدیث الشریف، ص: ۱۰۷ـ۱۱۲)
2- دوسرا بہانہ بعض لوگوں نے یہ ایجاد کیا ہے کہ فلاں روایت لفظاً اگرچہ موضوع ہے، لیکن معناً صحیح ہے، اس لیے اسے حدیث کے طور پر بیان کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، نعوذ باللہ!مثلاً: کہتے ہیں کہ ’’علماء أمتي کأنبیاء بني إسرائیل‘‘(میری امت کے علماء، بنی اسرئیل کے انبیاء کی مانند ہیں)، اس روایت کا معنی درست ہے، اور چونکہ روایت بالمعنی بالاتفاق جائز ہے، اس لیے گویا یہ بھی حدیث ہے، سبحان اللہ العظیم! حالانکہ کسی روایت کا مدعا صحیح ہونے اور اس کے مروی بالمعنی ہونے کے درمیان زمین وآسمان کا فرق ہے، اس نکتے کی مزید وضاحت کے لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی ’’لسان المیزان‘‘ اور سیوطی رحمہ اللہ کی ’’ذیل الموضوعات‘‘ دیکھیں۔ یہ اجماعی قاعدہ ہے کہ صرف اس بنا پر کسی بات کو حدیث نہیں کہا جاسکتا کہ وہ حق و صواب ہے، بلکہ حدیث کہنے کے لیے دو شرطیں ہیں: ۱-بات کا حق ہونا۔ ۲-نسبت ثابت ہونا۔ علاوہ ازیں مذکورہ روایت کے بارے میں یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں کہ اس کا مدعی درست ہے، ’’لیس بحدیث‘‘ (بزبان بنگلہ) نامی کتاب میں ہم نے اس کی مفصّل تحقیق ذکر کی ہے۔
3-تیسرا بہانہ یہ گھڑلیا گیا ہے کہ فنی طور پر گو حدیث صحیح نہ ہو، لیکن کشف سے صحت معلوم ہو تو حدیث کو بیان کیا جا سکتا ہے، جب کہ یہ مسلّمہ اصول ہے کہ کشف والہام اور خواب ومنام، علمی و عملی امور میں حجت نہیں ہیں۔
4-اس بات کا بھی سہارا لیا جاتا ہے کہ فضائل میںضعیف حدیث قابلِ قبول ہے، اس لیے فضائل میں روایت کو جانچنے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں، بلکہ منکر یا موضوع سب روایتیں فضائل میں چل جاتی ہیں، حالانکہ فضائل میں جو ضعیف احادیث قابلِ قبول ہیں، ان سے موضوع، مطروح، واہی اور منکر المتن روایات بالاجماع مستثنیٰ ہیں۔
واقعہ یہ ہے کہ آج کل عوام صرف موضوع حدیثیں بیان ہی نہیں کرتے، بلکہ احادیث گھڑتے بھی ہیں، لیکن ان کو علم بھی نہیںہوتا، اور لاشعوری طور پر وضعِ حدیث کے گناہ کا شکا رہو جاتے ہیں۔ مثلاً:کسی بزرگ کی بات کو بے دھڑک حدیث بنا دیا، یا کوئی بھی بات اچھی لگی، تو کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ تساہل کا یہ عالم ہے کہ بعض لوگ، موضوع روایتیں مزے لے کر بیان کرتے ہیںاور جب متوجہ کیا جائے تو سکون سے کہہ دیتے ہیں کہ: ’’ہمیں تو علم نہیں تھا کہ یہ روایت‘ موضوع ہے !!‘‘ گو یا جس روایت کے موضوع ہونے کا علم نہ ہو، اسے بیان کرنے میںکوئی مضائقہ نہیں ! اسے کہتے ہیں: ’’عذرِ گناہ بدتر ازگناہ‘‘۔ ایسے لوگوں سے ادب کے ساتھ کہا جائے کہ کیاآپ کو یہ علم ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یا حسن ہے، یاقابل بیان ہے ؟ اگریہ بھی معلوم نہیں تو پھر کیوں بیان کر رہے ہیں؟ حدیث بیان کرنے کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اس کے صحیح، یاحسن، یاضعیفِ صالح للعمل والروایۃ ہونے کا علم ہو، شریعت نے تو یہ اصول طے کیا ہے :
’’اتقوا الحدیث عني إلا ما علمتم۔ ‘‘ (سنن الترمذي:کتاب التفسیر، باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأیہ۔ المسند للإمام أحمد، رقم الحدیث : ۲۶۷۵، عن ابن عباسؓ)
یعنی ’’میری نسبت سے جس بات کا حدیث ہونا معلوم ہو، صرف وہی بیان کرو ۔‘‘
یہ بات درست نہیں کہ جس روایت کے موضوع ہونے کا علم نہ ہو، اسے بیان کر سکتے ہیں، اس طرح تو معاملہ بہت آسان ہوجائے گا، لوگوں کے جی میں جو کچھ آیا کہتے رہیں گے اور استفسار پریہ کہہ دیں گے کہ ہمیںتو اس کے موضوع ہونے کا علم نہیںتھا۔ بہرحال یہ بھی ایک بہانہ ہے کہ مجھے اس روایت کے موضوع ہونے کا علم نہیں تھا، میں نے تو کسی کتاب میںپڑھی تھی، اس لیے بیان کردی۔ اس بہانے کی بنیاد پر احادیث کے بیان میںتساہل سے کام لیا جاتا ہے۔ ان حیلوں بہانوں پر مدلل اور باحوالہ نکیر ’’مرکز الدعوۃ الإسلامیۃ‘‘ (ڈھاکہ، بنگلہ دیش) سے ’’الأحادیث الشائعۃ الموضوعۃ‘‘ سے متعلق شائع شدہ اہم کتاب ’’لیس بحدیث‘‘(بزبانِ بنگلہ)کی ابتدا میں بندہ کے مقدمہ میں موجود ہے۔
مختلف فیہا مسائل کے میدا ن میں بھی علومِ حدیث کے اصولوں کو حزم واحتیاط اور بصیرت کے ساتھ منطبق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں بھی عملاًیہ فیصلہ کرلیا گیا ہے کہ علومِ حدیث کے اصولوں کو منطبق نہیںکرنا ہے، بہت کم لوگ مختلف فیہا مسائل میںسلیقے کے ساتھ دلائل بیان کرتے ہیں۔ عام طور پر پیشِ نظریہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مخالف کا جواب دے دیا جائے، اگر وہ کسی اور طریقے سے ہوگیا تو بس کام ختم، اگر ضرورت پیش آ جائے تو علومِ حدیث کابھی کوئی اصول بیان کردیا جائے، لیکن مقصد بنا کر ان مباحث کا علمی حق ادا کرنے میںانتہائی تساہل برتا جاتا ہے، اورعمومی طرزِ عمل سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا بذاتِ خود ہمیںیہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی مخالفت کرے تو اسے خاموش کرنے کے لیے کچھ معلومات حاصل کر لینا کافی ہے۔
علمی امورمیں یہ سب سے بڑا عملی میدان ہے جس میں علومِ حدیث کو منطبق کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ اس طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔ اکثر طلبہ نے علی وجہ البصیرۃ فیصلہ کر لیا ہے کہ علومِ حدیث کو ہاتھ نہیںلگانا، گویا یہ شجرہ ممنوعہ ہے، إلا ما شاء اللہ تعالٰی، کچھ طلبہ ضرور ایسے ہیں، جو اہتمام کرتے ہیں، اور ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق سے نوازے۔ عمومی طور پرصورتحال یہ ہے کہ چوں کہ ’’مشکاۃ المصابیح‘‘ کے بعد اگلے سال حدیث کی بہت سی کتابیںپڑھنی ہوتی ہیں، اس لیے ’’ مشکاۃ المصابیح‘‘ کے درجہ میں ایک کتاب ’’شرح النخبۃ‘‘ (نزھۃ النظر في توضیح نخبۃ الفکر للحافظ ابن حجر رحمہ اللہ) پڑھ لیتے ہیں، لیکن کیا دورۂ حدیث کے پورے سال میں کبھی طالب علم کو ’’شرح النخبۃ‘‘ کھول کردیکھنے کی نوبت آتی ہے ؟! یہ نظریہ بن گیا ہے کہ علومِ حدیث ایک مستقل فن ہے، اسے حدیث سے الگ رکھنا چاہیے، اس کا اپنا مقام ہے، اور اسے ’’شرح النخبۃ‘‘ میں پڑھ لیا گیا ہے، بلکہ ’’شرح النخبۃ‘‘ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس ’’تیسیر مصطلح الحدیث‘‘ اور اس طرح کی بعض کتابیں دیکھ لی جائیں تو علومِ حدیث کا حق ادا ہوجائے گا، ضرورت تو اس کی ویسے بھی کہیں نہیں پڑتی!! بعض طلبہ برکت کے لیے شروع سال میں کسی ’’ ثبت‘‘ (مجموعۂ اسانید) سے ایک سند پڑھ دیتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگئی، اس میںبھی نہ ناموں کے ضبط کی طرف توجہ، نہ تصحیحِ عبار ت کی طرف التفات!
بہرکیف ان چاروں میدانوں میں علومِ حدیث کو منطبق کرنے کی ضرورت تھی، لیکن بزبانِ حال اور عملاً گویا یہ فیصلہ کرلیا گیاہے کہ ہم نے ان علوم کو منطبق نہیں کرناہے، برکت کے لیے برائے نام گزر ہو جائے تو مضائقہ نہیں، اہتمام کے ساتھ حق ادا کرنے والے بہت کم ہیں، جن کے لیے پہلے بھی إلا ماشاء اللہ کہہ کر استثناء کیا گیا ہے، کثّر اللہ أمثالَہم !
علومِ حدیث کومنطبق کرنے کا پانچواں مید ان‘ منکرینِ حدیث اور مستشرقین کے اعتراضات کی تردید ہے، بلکہ صرف علم حدیث نہیں، تاریخ، فقہ، سیرت، اور تمام علومِ دینیہ پر معاندین کی طرف سے پیدا کردہ شکوک و شبہات کے صحیح رد کے لیے ’’علم الإسناد‘‘ میں مہارت ضروری ہے، ’’علم الإسناد‘‘ میںمہارت کے بغیر یہ عمل تقریباً ناممکن ہے۔ مستشرقین کے خلاف انہی اہلِ علم نے کام کیا ہے جن کو ’’علم الإسناد‘‘ میں دلچسپی رہی ہے، کوئی ایسا صاحبِ علم نہیں ملے گا جو علومِ حدیث میں دلچسپی نہ رکھتا ہو اور اس نے مستشرقین کے خلاف کوئی وقیع کام کیا ہو۔
علومِ حدیث کے استعما ل اور تطبیق میںافراط و تفریط کی وجوہ، کثیر اور متنوّع ہیں، پیش نظر مضمون میں ان سب وجوہ کا استقصا مقصود نہیں، بلکہ وجوہِ افراط وتفریط میںسے صرف انتہائی عام اور واضح وجوہ کا ذکر کیا جارہا ہے، ورنہ ان کی فہرست بہت طویل ہے، مثلاً : ’’ علمِ عللِ حدیث‘‘ کے استعمال میںافراط و تفریط، ’’علمِ جرح و تعدیل‘‘ کے استعمال میں افراط و تفریط۔ ’’کتبِ مصطلح‘‘ کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ اور متقدمین کی کتابوں کے ساتھ کیا صنیع ہونا چاہیے؟ ایسے بہت سے امور ہیںجن میں علومِ حدیث کی تطبیق کرنے والے افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں، اس عنوان کے تحت ان سب وجوہ کا ذکر کرنا مقصود نہیں، بلکہ چند اہم وجوہ کا ذکر کیا جا رہا ہے:
اِفراط سے مراد ہے: حد سے آگے بڑھ جانا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیزکی حدود رکھی ہیں: ’’ قد جعل اللہ لکل شيء قدرا‘‘ (اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک انداز مقرر رکھا ہے۔) اگر آپ نے ان حدود کا خیال نہ رکھاتو پھر آپ نے ان علوم کا وہ استعمال نہیں کیا جس کی وجہ سے اس کا استعمال جائز تھا۔
اِفراط کے بہت سے مظاہر ہیں، علومِ حدیث (یعنی عرفِ عام میںجن علوم و فنون کو ’’ علومِ حدیث‘‘ کہا جاتا ہے، ان) کا اصل میدان ہے: ’’نقد أخبار الأحاد التي حالُ أسانیدِھا تحت النظر‘‘ ( یعنی ان اخبارِ آحاد کی چھان پھٹک کرنا، جن کی اسانید کا حال قابلِ غور ہے)۔ افراط کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آدمی یہی اصل مقصد بھول جائے، اور اس اصل میدان کو نظر انداز اورفراموش کر کے نقدِ اخبارِ آحاد کے ان اصولوں کو متواترات، مسلّمات اور عملِ متوارث سے ثابت شدہ امور پر بھی منطبق کرنے کی کوشش کرے، اور یہ مطالبہ کرنے لگے کہ ان امور کی بھی خبرِ واحد کی مانند صحیح سند ہونی چاہیے، یہ افراط کا خطرناک مظہر ہے، اسی نکتے کو علامہ محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یوں بیان کیا ہے :
’’کان الإسناد لئلا یدخل في الدین ما لیس منہ، لا لیخرج من الدین ما ثبت منہ بعمل أہل الإسناد۔‘‘ (یعني أھل العلم وحملتہ في العصور الذھبیۃ وفي الأمصار الإسلامیۃ)۔‘‘
’’اسناد کی غرض تو یہ ہے کہ دین کوئی ایسا امر داخل نہ ہو جو دین کا حصہ نہیں، یہ مقصد نہیں کہ خود اہلِ اسناد (سنہرے ادوار اور عہد میں مسلم ممالک کے اہلِ علم اور حاملینِ علم دین) کے عمل سے ثابت شدہ امر کو دین سے خارج کردیا جائے۔‘‘
(شاہ صاحبؒ کے اس ارشاد کی تفصیل کو سمجھنے کے لیے ملاحظہ فرمائیے: فیض الباري، نیل الفرقدین، بسط الیدین، معارف السنن، التعلیقات الحافلۃ علی الأجوبۃ الفاضلۃ للأسئلۃ العشرۃ الکاملۃ، ص:۲۳۸، نیز شیخ محمدعوامہ حفظہ اللہ کی دراسۃ حدیثیۃ اور أثر الحدیث الشریف)
یعنی اسناد کا مقصدتو یہ تھا کہ جو چیز‘ دین کا حصہ نہیںہے، اس کو دین میںداخل ہونے سے روکا جائے، جب کوئی شخص حدیث بیان کرے تو اس سے مطالبہ کیا جائے : من حدّثک؟ (آپ سے یہ حدیث کس نے بیان کی؟) اگر اس کے پاس ثبوت نہ ہوگا تو : بَقِيَ، یعنی: بَقِيَ حیرانًا، ساکتًا، مُفْحَمًا، مَبْہُوْتًا۔(یعنی وہ حیران پریشان، خاموش اور مبہوت رہ جائے گا )۔
ا سناد کا مقصد تویہ تھا، جبکہ جوامور دین میں مسلّمہ ہیں، مشہور و مُتَلَقّٰی بالقبول ہیں اور ان پر اہلِ دین اور حاملینِ علمِ دین کا اجماع و توارث ہے، ان کے لیے اس نوع کی سند کی ضرورت نہیں؛کیونکہ ایسے امور میں اجماع و تلقی ہی سب سے بڑی سند ہے۔ اب اگر کوئی ایسے امور کی سند تلاش کرنے لگے اور جب (اصطلاحی )سند نہ ملے تو اس کا انکار کرنے لگے تو یہ علومِ حدیث کاان کی حدو د سے خارج اور ناجائزاستعمال ہوگا۔
ہر دور کے حاملینِ علم کے اعتقادی توارث سے جو عقائد ثابت ہیں، ہر دور کے حاملینِ علم کے فکری توارث سے جو افکارثابت ہیں، اور ہر دور کے اہلِ علم کے اجماع سے جو مسائل اور احکام ثابت ہیں، ان کے لیے اصطلاحی اسناد کی ضرورت نہیں، اب اگر کوئی علومِ حدیث کے اصول( جن کا مقصد، نقدِ اخبارِ آحاد ہے، ان) کو اِن مسلّمہ امور پربھی منطبق کرنا شروع کردے گاتو یہ ان اصولوں کی حدود سے تجاوز ہوگا۔
الغرض علومِ حدیث کے وہ قواعد‘ جو خبر واحد کی جانچ پڑتال کے لیے وضع کیے گئے تھے، ان کو مسلّمات، اجماعیات، متواترات اور متوارثات میں استعمال کرنا بڑا خطرناک معاملہ اور نہایت غلو ہے؛ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص ایساکرے گاتو عین ممکن ہے کہ ایسے مسلّمات میں کوئی اصطلاحی سند نہ مل سکے ؛کیونکہ اجماع منعقد ہونے کے بعداُن کے نقلی دلائل (جو اخبار آحاد کی شکل میں تھے، ان ) کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا؛اس لیے کہ اجماع خود دلیل ہے، نیز سنتِ متوارثہ، سنتِ خلفائے راشدینؓ، اور توارث و تواترِ مستمر از خیر القرون بذا ت خود مستقل دلائل ہیں ؛اس بنا پر ان امور کے متعلق الگ طور پر حدّثنا اور أخبرنا کے سا تھ مروی کوئی روایت اگر موجود بھی تھی تو اس کی حفاظت کا زیادہ اہتمام نہیں کیا گیا؛ کیونکہ اس سے بڑی دلیل یعنی اجماع موجود ہے، اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ تو اجماعی ہوتا ہے، لیکن اس پر کوئی حدیث نہیں ملتی، یا حدیث مل تو جاتی ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ نہیں ملتی، توجن لوگوں میں حکمت وفقہ کی کمی ہوتی ہے، اورجو علومِ حدیث کا غلط استعمال کرتے ہیں، وہ اس مسئلہ کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیںکہ اس کی دلیل کے طور پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے ! علومِ حدیث کو اس طریقے سے استعمال کرنا بہت خطرناک طرزِ عمل ہے۔
اس غلط استعمال اوراس افراط میں جو حضرات پیش پیش ہیں، ان میں طبقہ علماء میں سب سے آگے شیخ ناصرالدین البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ کی علمی تقصیرات میں سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ انہوں نے علومِ حدیث کو اپنے دائرے سے باہر غیر محل میںاستعمال کیا ہے، چنانچہ کئی مسائل میںان کے ہاںجمہور امت سے شذوذ آگیا ہے، مثلاً: شیخ البانی کے ہاں آپ کو یہ غلط اور منکر مسئلہ مل جائے گاکہ بلاوضو‘ مصحف کو چھونا جائز ہے، ایسی بے تکی بات بھی مل جائے گی کہ کوئی شخص نماز چھوڑ دے تو اس کی قضا کی ضرورت نہیں۔ ان مسائل میں یا اس نوع کے دیگر مسائل میں ان سے شذوذ واقع ہونے کی وجہ یاتو علومِ حدیث کی غلط تطبیق ہے، یا علمِ اصولِ فقہ کے قواعد کا غلط استعمال ہے۔ اس نوع کے مزید غلط مظاہر کا مشاہدہ کرنے کے لیے ان کی ’’کتاب التراویح‘‘ اور ’’ کتاب الحجاب‘‘ کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔
معلوم نہیں کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب‘ حجاب کو ثابت کرنے کے لیے لکھی ہے، یا اس حکم کو پامال کرنے کے لیے؟!انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ چہرے کا پردہ ثابت نہیں، حالانکہ اصل پر دہ تو ہے ہی چہرے کا، حجاب کا حکم تو سنہ پانچ ہجری میںنازل ہواہے۔ سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے ستر کا حکم تھا یا نہیں؟!یقیناً تھا، تو پھر حجاب کا کیا نیا حکم آیا؟یا پھر یہ تسلیم کیا جائے کہ حجاب کے حکم سے پہلے خواتین، ستر کوچھپانے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں؟!
شیخ البانی کی کتاب کا سرسری مطالعہ کرنے والے تو کہیں گے کہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے سب ٹھیک ہے، بہت سی ایسی کتابوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جن میں چہرے کے پردے کو فتنے کی شرط کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے، اور کئی ایسی کتابوں کا حوالہ دیا جاسکتا ہے جن میں ’’إلا ماظہر‘‘ کی تفسیر میں ’’الوجہ والکفین‘‘ کا ذکرکیا گیا ہے، پھر شیخ البانی نے کیا برا کیا؟!
تفقُّہ اور تأنّی کی کمی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے، علم کے لیے تفقُّہ اور تأنّی کی ضرورت ہے، اگر تفقّہ، حلم او رتأنّی کا استعمال کیا جائے تو سب واضح ہوجاتا ہے۔ تفقُّہ کا استعمال نہیںہو گا تو یہی نتیجہ ہوگا کہ بہت سے متفق علیہا مسائل کو اختلافی بنادیا جائے گا، مثلاً:
1-کچھ لوگ کہیں گے کہ معراج کا مسئلہ بھی اختلافی ہے ؛ کیوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے : ’’ما فُقِد جسدُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم في لیلۃ الإسراء‘‘ (اسراء کی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسدِ مبارک (اپنے بستر سے)غائب نہیں ہوا) یہ جملہ کہیں عربی میں لکھا ہوا دیکھا تو بس اتنا کافی سمجھ لیا جائے گا۔ اس جملے کا ماخذ کیا ہے؟ اس کی متصل سند موجود ہے یا نہیں؟ اور اس کی نسبت ثابت ہے یا نہیں؟ان لوگوں کے نزدیک ان جہتوں کی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہوگی!
2- حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ معراج کو خواب کہتے تھے۔ جو لوگ تفقُّہ کو کام میں نہیں لائیں گے وہ اس مسئلہ کے بارے میں بھی کہیں گے کہ واقعۂ معراج کے متعلق تودورِ صحابہؓ میں ہی اختلاف ہوگیا تھا، حالانکہ تحقیقی بات یہ ہے کہ ان حضرات کی طرف ان روایات کی نسبت ہی درست نہیں ہے۔
حلم اور تأنّی نہ ہوتو تحقیق کاعمل انجام نہیں دیا جاسکتا، اور ’’المشي مع الشائعات‘‘ (یعنی عام پھیلی ہوئی باتوں کے پیچھے چلنا) تحقیق کے موانع میں سے بڑا مانع ہے۔ شائعات کو مسلّمات پر قیاس کرنا درست نہیں، شائعات میں تو توقف کرنا چاہیے، انہیں جانچنا پرکھنا چاہیے، اور ان کاماخذ تلاش کرنا چاہیے۔ اگر کوئی سراغ مل جائے تو اس کے سیاق و سباق کو غور سے دیکھنا چاہیے، اورمظان و غیر مظان میں اس کی تفصیل دیکھنی چاہیے۔
کچھ عرصہ قبل ایک بنگلہ اخبار میں مضمون چھپا، جس کا عنوان یوں تھا: ’’قرآن کے پردے کو برقع میں کس نے تبدیل کیا؟‘‘ اس میںچہرے کے پردے کا انکا ر کیا گیا تھا، اور طرح طرح کی خرافات ذکرکی گئی تھیں، اور اس کا مواد شیخ البانی کی مذکورہ کتا ب سے لیا گیا تھا ( غالباً شیخ البانی کی اس کتاب کا انگریزی یا بنگلہ میں ترجمہ ہوا ہے)، یہ بہت لمبا چوڑا مضمون ہے، کوئی پڑھے گا تو متاثر ہوجا ئے گا؛ کیونکہ اس میں مختلف کتابوں کے حوالے ہیں، تفسیر، حدیث اور فقہ کی کتابوں کے حوالے ہیں، اور اگر آپ ان حوالوں کی مراجعت کریں گے تو نظر آئے گا کہ وہ حوالے توان کتابوں میں موجود ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ’’إلا ماظہر‘‘ کی تفسیر میں ’’الوجہ والکفین‘‘ کہا ہے، اب آپ اس کے جواب میں کہیں گے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے دوسری تفسیر منقول ہے، تو گویا یہ مسئلہ دورِ صحابہؓ میں مختلف فیہا ہوگیا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ دونوں ہی حضرات اس بات کے قائل ہیںکہ چہرے کا پردہ واجب ہے۔ ہمارے مرکز کے ساتھی مولانا زکریا عبداللہ نے اس مضمون پر تبصرہ لکھا ہے، وہ پڑھ کر دیکھیں گے تو حقیقت واضح ہوگی۔ آدمی اگر صبر سے کام لے اور تلاشِ حقیقت کے لیے جستجو جاری رکھے تو اطمینان حاصل ہوجاتا ہے۔ بے صبری اور تحقیق کا ایک ساتھ جمع ہونا محال ہے، بغیر صبر کے مواد بھی جمع نہیں کیا جاسکتا، جبکہ مواد جمع کرنے کے بعد بھی تحقیق کے کتنے دقیق مراحل ہیں؟!
ایک دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جو تفسیر منقول ہے کہ انہوں نے ’’وَلَایُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا‘‘ کی تفسیر میں فرمایا: ’’الوجہ والکفین‘‘ سوال یہ ہے کہ یہ تفسیر ’’زینۃ‘‘ کی ہے یا ’’اِلَّا مَا ظَہَرَ‘‘ کی؟ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام میں لکھا ہے کہ: ’’یہ احتمال بھی ہے کہ یہ تفسیر ’’زینۃ‘‘ کی ہو۔‘‘ (۴/۵۳۸) اب اگر آپ یقین سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ’’اِلَّا مَا ظَہَرَ‘‘ کی تفسیر ہے تواس کی کیا دلیل ہے ؟ یہ ’’زِیْنَتَھُنَّ‘‘ کی تفسیر کیوں نہیں ہوسکتی ؟ کون سے قوی قرینہ کی بنا پر آپ اسے ’’اِلَّا مَا ظَہَرَ‘‘ کی تفسیر کہہ رہے ہیں؟ کیا کہیں یوں آیا ہے: ’’المراد بما ظہر منھا: الوجہ والکفین‘‘ ؟! کوئی ایک عبارت دکھادیں! نہیں دکھا سکتے۔ روایت میں یوں ہے کہ انہوں نے آیت ’’وَلَایُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا‘‘ پڑھ کر فرمایا: ’’الوجہ والکفین‘‘۔ اب اکثر لوگوں نے اس سے یہ سمجھا کہ مراد ’’مَا ظَہَرَ مِنْہَا‘‘ کا مصداق بتانا ہے، اس طرف خیال نہ گیا کہ اس سے ’’زینۃ‘‘ کی تفسیر بھی تو مراد ہوسکتی ہے۔ بہرحال یہ بتایا جائے کہ یہ ’’زینۃ‘‘ کی تفسیر کیوں نہیں ہوسکتی؟ اس کی دلیل بتائیں، ورنہ جب ایک جہت کی ترجیح نہیں ہوسکتی تو اس سے استدلال نہ کریں؛ کیونکہ ’’إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال‘‘ (جب احتمال کا دروازہ کھل گیا تو استدلال باطل ہوگیا) اور اگر ترجیح دینی ہے تو اس کی تصریح یا وجہ ترجیح دکھائیں۔
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ا س تفسیر کے لیے جو حوالے دیے ہیں، ان میں ایک حوالہ ’’مصنف ابن أبي شیبۃ‘‘ کا بھی ہے، جب ’’مصنّف‘‘ کی مراجعت کی گئی تو وہاں روایت اس طرح ملی : ’’وَلَایُبْدِیْنَ زِیْنَتَھُنَّ ، قال: الکف ورقعۃ الوجہ۔‘‘ (مصنف ابن ابی شیبہ، ۳/۳۸۴)’’إلیٰ آخرہ‘‘ بھی نہیں ہے۔ بظاہر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو اس مقام میں یہ روایت مستحضر نہیں تھی، ورنہ وہ ضرور اس سے استدلال کرتے۔ مولانا زکریا عبداللہ سلمہ المولی الکریم نے اپنے مقالے میں اس روایت کا ذکر کیا ہے، اور اس کی روشنی میں بات واضح ہے کہ جس ’’ زینت‘‘ کو ظاہر کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس میں چہرہ اور ہتھیلیاں داخل ہیں۔ اب حجاب کے بعد بھی اگر جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہوجائے، مثلاً: نقاب ہٹ جائے، یا پیر کی جانب سے کپڑا ہٹ جائے اور زیور ظاہر ہوجائے تو وہ معاف ہے۔ اسی کو فرمایا: ’’اِلَّا مَا ظَہَرَ مِنْہَا‘‘
اس کے علاوہ اس بات پربہت سے قرائن ہیںکہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ مقصد ہرگز نہیں تھا کہ عورت، چہرہ کھلا رکھے۔ ویسے بھی سوچنے کی بات ہے کہ چہر ہ کھلا رہے تو پردہ کس چیز کا نا م ہے؟! معمولی عقل بھی استعمال کی جائے تو بات سمجھ آسکتی ہے۔
شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو ’’ مصنف ابن أبي شیبۃ‘‘ کا حوالہ نہیں دینا چاہیے تھا؛ کیوں کہ اس روایت میںان کی دلیل نہیں ہے؛ بلکہ یہ روایت ان کے خلاف جاتی ہے، اورجب حوالہ دیا ہے تو وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ وہاں روایت کے الفاظ ا س اندا ز سے آئے ہیں۔
مذکورہ تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ علومِ حدیث کا ایک غلط استعمال و طریقۂ تطبیق تو یہ ہے کہ اس میں تفقُّہ حاصل کیے بغیر قواعد کا سطحی استعمال کیا جائے، لیکن اس مقام میں یہ نکتہ زیرِ بحث نہیں ہے، بلکہ یہاں عمومی افراط وتفریط زیرِ بحث ہے، یعنی عرفِ عام میں جن علوم کو ’’ علومِ حدیث‘‘ کہا جاتا ہے، ان کا غیر موضوع لہ میں استعمال؛ کیونکہ ان علوم کا موضوع، اخبارِ آحاد کا نقد ہے، اگر اِجماعیات، مسلّمات اور متوارثات میں ان کا استعمال شروع کیا گیا تو یہ افراط کا خطرناک ترین مظہر ہوگا۔ (جاری ہے)