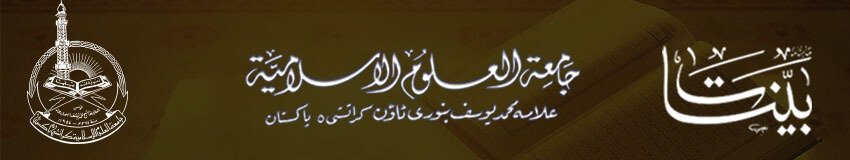
قرآن وحدیث میں حصولِ علم کی جو کچھ ترغیب وفضائل وارد ہوئے ہیں، وہ کسی بابصیرت شخص سے مخفی نہیں ہیں۔ فضائل وترغیب سے کسی چیز کا ندب واستحباب ثابت ہوجاتاہے، بعض روایات میں اس کے حاصل نہ کرنے پر وعید بھی وارد ہوئی ہے، اسی طرح بعض نصوص میں اس کو لازم بھی قرار دیاگیاہے، جس سے واضح ہوجاتاہے کہ علم حاصل کرنا شریعت کی نظر میں صرف مستحب یامندوب ہی نہیں ہے، بلکہ واجب اور ضروری بھی ہے۔
ان نصوص کے ظاہر کودیکھاجائے تواگر چہ معلوم ہوتاہے کہ ہر قسم کے علم کا حاصل کرنا واجب اور ضروری ہو، لیکن اس بات پر بھی اُمت کا اتفاق رہاہے کہ ہرشخص پر ہر قسم کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کے مختلف حصےہیں، جن کےاحکام بھی مختلف ہیں، چنانچہ علم کاایک حصہ وہ ہے جس کاعلم ہرشخص کےلیےلازم ہے، جس کو فرضِ عین کہا جاتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو ہرشخص کی ذمہ داری تونہیں ہے، تاہم مجموعی طورپر امت اس کی ذمہ دار ہے، اس کو ’’فرضِ کفایہ‘‘ کہا جاتا ہے۔ ایک حصہ وہ ہے جو ان دونوں سے زائد ہے، اس کو ’’مستحب‘‘ کہا جاتا ہے، اسی طرح اور بھی مختلف درجات ہیں۔ ’’أشباہ‘‘میں ہے:
’’فائدۃ: تعلم العلم يکون فرض عين، وہو بقدر ما يحتاج إليہ لدينہ۔ وفرض کفايۃ، وہو ما زاد عليہ لنفع غيرہ۔ ومندوبًا، وہو التبحر في الفقہ وعلم القلب۔ وحرامًا، وہو علم الفلسفۃ والشعبذۃ والتنجيم والرمل وعلم الطبيعيين والسحر، ودخل في الفلسفۃ المنطق۔ ومن ہٰذا القسم علم الحرف والموسيقي۔ ومکروہًا، وہو أشعار المولدين من الغزل والبطالۃ۔ ومباحًا، کأشعارہم التي لاسخف فيہا۔‘‘
ترجمہ: ’’دینی ضرورت کی حد تک علم حاصل کرنافرضِ عین ہے، اس سے زائد دوسروں کے نفع کےلیے علم حاصل کرنافرضِ کفایہ ہے۔ فقہ اورتصوف میں مہارت پیداکرنامستحب ہے۔ فلسفہ، منطق، شعبدہ بازی(مداری فن )، علمِ نجوم، علمِ رمل، علوم طبیعیات اورعلمِ سحر بشمول علمِ حرف اورعلمِ موسیقی، یہ سب حرام ہیں۔ مولدین (متاخرین) کے اشعار، غزلیں، عشقیہ اشعارمکروہ ہیں، البتہ ان لوگوں کے وہ اشعار جن میں کوئی بری بات نہ ہو، وہ مباح ہے۔ ‘‘
ذیل میں بقدرِ ضرورت اس کی تفصیل لکھی جاتی ہے:
اس حد تک علم حاصل کرنا فرضِ عین ہے، جس پر اپنے دینی واجبات وفرائض کی تحصیل موقوف ہو، اس کے تحت نماز، روزہ اورغسل وطہارت کے وہ موٹےموٹےمسائل داخل ہوجاتے ہیں۔ ا ن میں سے جن مسائل کے ساتھ ہر شخص کا تعلق ہو، وہ ہر شخص کے لیے سیکھنا ضروری ہیں، اور جن مسائل کا تعلق خاص افراد کےساتھ ہو، ان کا سمجھنا ان خاص افراد کے لیے واجب ہے۔ اسی طرح جو مسائل ہروقت پیش آتے ہوں، ان کا علم ہر وقت کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے اور جو خاص حالات واوقات میں پیش آتے ہوں، ان کا علم انہی مواقع کےلیےضروری ہے، لہٰذا کوئی شخص صاحبِ نصاب ہو، تو اس کے لیے زکوٰۃ کے ضروری مسائل سیکھنا لازم ہے۔ کوئی شخص صاحبِ استطاعت ہے، اس پر حج کے احکام جاننا لازم ہے۔ کوئی شخص تجارت وملازمت کررہا ہے، اس پر اپنی تجارت وملازمت کی حد تک ضروری ضروری باتوں کا شرعی حکم جاننا واجب ہے۔ کوئی شخص زراعت وحِرفت کا مشغلہ رکھتا ہے تو اس پر اپنے متعلقہ شُغل سے متعلق شرعی مسائل واحکام معلوم کرنا ضروری ہے۔
اپنی ضرورت واحتیاج سے بڑھ کر دوسرے مسلمانوں کی ضرورت واحتیاج کی باتوں کا جاننا فرضِ کفایہ ہے، اس کے تحت وہ تمام علوم داخل ہوجاتے ہیں جن پر کوئی دینی یا دنیوی ضرورت وحاجت موقوف ہو۔ دینی علوم میں اس کی مثال علمِ فقہ کے وہ مسائل ہیں جن کےساتھ خود اس جاننےوالے کاواسطہ پیش نہ آتا ہو، لیکن عام امت یا اس کے کچھ افراد کی ضرورت اس کےساتھ وابستہ ہو، مثال کے طور پر زید خود صاحبِ نصاب نہیں ہے، لیکن وہ صاحبِ نصاب افراد کی ضرورت پوری کرنے کےلیے زکوٰۃ واجب ہونے اور اس کی ادائیگی وغیرہ سےمتعلق مسائل معلوم کرتا ہے۔ وہ صاحبِ استطاعت نہیں ہے کہ اس کی طرف حج کا حکم متوجہ ہو، لیکن صاحبِ استطاعت افراد کےلیے حج کے مسائل جاننے کی کوشش کرتاہے، یہ سب فرضِ کفایہ ہے۔ علامہ سنان الدین اماسیؒ اور علامہ ابن عابدین ؒ کے ہاں اس ضمن میں علمِ نحو، لغت، کلام، قراءات، علمِ اصولِ حدیث میں اسنادسے متعلق مباحث، علمِ میراث، معانی، بیان، بدیع، اصول اور علمِ ناسخ ومنسوخ سب داخل ہیں۔ دنیوی علوم وفنون میں اس کے تحت وہ تمام فنون داخل ہوجاتے ہیں، جن پر ملت کی بقاء وحفاظت اور اس کی درپیش ضروریات کی تکمیل موقوف ہو۔ ریاضی، طب، تجارت وحرفت، زراعت ومعیشت اور ایک حد تک سائنس وٹیکنالوجی وغیرہ سب اس کے تحت داخل ہوجاتے ہیں۔
علوم کا تیسراحصہ وہ ہے جو مندوب اور مستحب ہے، یہ وہ حصہ ہے جو فرضِ عین اور کفایہ کی مقدار سےزائد ہو۔
علوم کی چوتھی قسم یا چوتھا حصہ وہ ہے جو ’’حرام‘‘ ہیں، اس کے تحت ’’درِمختار‘‘ وغیرہ کتابوں میں درج ذیل علوم کو گنوایا ہے:
۱: علمِ فلسفہ، درِمختار میں اسی کے ضمن میں علمِ منطق کو بھی داخل فرمایاگیاہے۔ ۲:شعوذہ(مداری پن)۔ ۳:علمِ نجوم۔ ۴:علمِ رمل۔ ۵:علمِ طبیعی۔ ۶:سحر کا علم۔ ۷: کہانت۔ ۸: علمِ حرف۔ ۹:علمِ موسیقی۔ (جن کے مقاصد و وسائل ہونے کے اعتبار سے اور اغراض و اہداف کے اعتبار سےاحکام میں تفصیل ہے، کما سیأتي)
معلومات کا چوتھا حصہ وہ ہے جو شرعی نقطۂ نظر سے مکروہ ہے، اس کے تحت ان شاعروں کے غزل واشعار داخل ہیں جو قدیم شعراء عرب کے بعد آئے ہیں۔
چھٹی قسم مباح ہے۔
یہ تقسیم اپنی جگہ بالکل درست ہےاور اکابر اہلِ علم نے اپنی اپنی کتابوں میں تھوڑے بہت فرق کے ساتھ اس کو ذکر فرمایاہے، تاہم ایک تو اس سے ’’علم کےاحکام‘‘ کا پورا ضابطہ سامنے نہیں آتا، کیونکہ زیادہ تر اس میں مثالوں پرا کتفا فرمایا گیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اپنے ماحول وزمانے کے مطابق دینی علوم وفنون کو ہی زیادہ تر پیش نظر رکھا گیا ہے، اس زمانے میں نہ عصری علوم کی بہتات تھی اور نہ ہی اس وقت کا معاشرہ اس قدر مادیت زدہ ہوچکا تھا، جتنا اس وقت ہمارا معاشرہ ہے، مادیت پسندی کی وجہ سے دنیوی علوم وفنون کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے اور بہت قلیل طبقہ وہ ہے جن کا دینی مقاصد کے تحت دینی علوم کی طرف التفات رہتا ہے۔
ان دو وجوہات کا نتیجہ ہے کہ اس تقسیم سے موجودہ دور کےتمام علوم وفنون کےاحکام معلوم نہیں ہوتے، جبکہ ضرورت اسی بات کی ہے، اس کے پیش نظر اس ناکارہ نے اصل مراجع کی طرف بار بار مراجعت کی اور ان کی روشنی میں کوئی جامع ضابطہ متعین کرنا چاہا، ذیل میں وہی ضابطہ ذکر کیاجاتاہے۔
علم حاصل کرنے کا کیاحکم ہے؟ کب اس کاحاصل کرنا ضروری، مستحب اور کب ناجائز وحرام ہوتا ہے؟ اس کے متعلق جامع ضابطہ درج ذیل نکات کی شکل میں ذکر کیا جاتا ہے:
1:علم حاصل کرنے کا حکم معلوم کے تابع ہے، یعنی :جس چیز کو معلوم کیا جاتا ہے، اس کی حیثیت کے مطابق علم حاصل کرنے کا حکم ہوگا۔ اگر کسی کے حق میں کوئی چیز فرضِ عین ہے اور جانے بغیر اس پر عمل نہیں کیا جاسکتا تو اس چیز کو جاننا بھی اس شخص کے حق میں فرضِ عین ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ فرضِ عین علم اَفراد اور حالات کےلحاظ سے مختلف ہوسکتا ہے، بعض افراد کے حق میں ایک چیز کاعلم فرضِ عین ہوتا ہے، دوسرے کےحق میں فرضِ عین نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض اوقات کسی چیز کا جاننا فرضِ عین ہوتا ہے، جبکہ دوسرےاوقات واحوال میں ایسا نہیں ہوتا، چنانچہ زکوٰۃ اور روزے کے واجب ہونے کےموقع پر ان کے ضروری مسائل کوجانناواجب ہے، دیگر مواقع پر ہرشخص کےذمہ یہ فرضِ عین نہیں۔ ہاں! البتہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہر مسلمان کے ساتھ متعلق ہیں، ان کاجاننا بھی ہر مسلمان پر ضروری ہے، مثال کےطور پر طہارت ونماز کے ضروری مسائل، اللہ تعالیٰ کےوجود، وحدانیت اور استحقاقِ عبادت جیسی ضروری اور بنیادی نوعیت کی باتیں۔
2:شریعت کےعلوم وتعلیمات کاتحفظ فرضِ کفایہ ہے، لہٰذا مستحب اور مندوب امور کاعلم ہرشخص کےلیے تو ضروری نہیں ہے، تاہم مجموعی طور پر اُمت کی ذمہ داری اوران کافرضِ منصبی ہے۔
3: اصل ضابطہ تویہی ہے کہ علم کا حکم معلوم کےحکم کےساتھ مربوط ہے، تاہم کچھ عناصر کی وجہ سے علم کاحکم معلوم کےحکم سے کچھ مختلف ہوجاتا ہے، ایسے امور بنیادی طور پر درج ذیل تین ہیں:
الف: مقاصد واہداف۔ بعض اوقات کوئی علم خود جائز، ضروری ہوتا ہے، لیکن ناجائز مقصود اس کے حاصل کرنےکو ناجائز بنادیتا ہے، اسی طرح بعض اوقات کوئی علم بذاتِ خود مکروہ ومذموم ہوتاہے، لیکن اچھی نیت اور بھلے قصد کی وجہ سے اس کی کراہت جاتی رہتی ہے اور وہ مندوب ومستحب تک ہوجاتاہے۔
چنانچہ متعدد احادیثِ مبارکہ میں دینی علوم کو حب جاہ یا مال کے جذبےسےحاصل کرنے کی سخت مذمت فرمائی گئی ہے، حالانکہ علومِ دین کا سیکھنا کم ازکم مستحب ہے، اسی طرح اگر مسلمانوں سے سحر کادور کرنا کسی اور محفوظ ومباح طریقے سے ممکن نہ ہو تو بقدر ِ ضرورت سحر سیکھنا بھی مباح ہے، حالانکہ یہ اصلاً حرام علوم میں سے ہے۔
ب:ذریعہ ووسیلہ۔ خارجی عناصر میں سے دوسری چیز ’’علم کے ذرائع ووسائل‘‘ ہیں، بعض اوقات خود کوئی چیز جائز بلکہ ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے حاصل کرنے کا طریقہ جائز نہیں ہوتا اور اسی ذریعے کی وجہ سے اس میں کراہت یا حرمت پیدا ہوجاتی ہے، مثال کے طور پر کوئی شخص علم دین سیکھنے کے لیے کوئی دینی کتاب چوری کرے اور اس سے علم سیکھتا رہے، اسی طرح ’’عصری علوم کے حکم‘‘ کے ذیل میں ذکر کردیا جائے گا کہ مخلوط نظامِ تعلیم کی وجہ سے بہت سے مفید دنیوی علوم کو سیکھنا بھی ممنوع ومذموم ہوجاتا ہے۔
ج:نتائج وثمرات: بسااوقات کسی بات کاعلم /فن بذاتِ خود تو ناجائز یاحرام مواد پر مشتمل نہیں ہوتا، لیکن بعض افراد کے حق میں اس کے برے نتائج وثمرات ظاہر ہوتے ہیں، ایسےافراد کےحق میں اس کاحاصل کرنا بھی ممنوع ومذموم بن جاتا ہے۔
رہا یہ سوال کہ اس تیسرے عنصر کی بنیاد پر کونسا علم بہرحال مکروہ وممنوع شمار ہوگا اور کونسا خاص افراد کے حق میں ممنوع قرار پائے گا؟
تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی علم تمام افراد یا اکثر افراد کے حق میں مضرثابت ہوتا ہے تو سب کے حق میں اس کی مذمت وممانعت کی جائے گی اور اگر کوئی علم ایسا ہے کہ وہ سب یا اکثر لوگوں کے حق میں ضرر وفساد کا باعث نہ ہو، لیکن بعض افراد اس کی وجہ سے بگڑتے ہوں تو ایسے علم کاحکم یہ ہے کہ جس کے حق میں فساد تک پہنچانے کا اندیشہ ہو، اس کے حق میں ممنوع قرار دیا جائے گا اور جس کےحق میں ایسا اندیشہ نہ ہو، اس کے حق میں اس کی اجازت دی جائے گی، تاہم دینی خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ متعلقہ مفاسد ومنکرات سےمتعلق بھی آگاہی دی جاتی رہے۔
’’علمِ نجوم‘‘ کےحکم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ’’إحیاء العلوم‘‘ میں ہے:
’’وإنما زجر عنہ من ثلاثۃ أوجہ: أحدہا أنہٗ مضر بأکثر الخلق، فإنہٗ إذا ألقي إليہم أن ہٰذہ الآثار تحدث عقيب سير الکواکب وقع في نفوسہم أن الکواکب ہي المؤثرۃ وأنہا الآلہۃ المدبرۃ۔‘‘
ترجمہ: ’’تین وجوہات کی وجہ سے علمِ نجوم ممنوع ہے :اول یہ کہ اکثرلوگوں کے حق میں یہ نقصان دہ ہے، کیونکہ جب ان کے دل میں آتاہے کہ یہ آثار ستاروں کی حرکت کے بعد پیداہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ بات جاگزیں ہوتی ہے کہ یہی ستارے ہی مؤثر، معبود اور تدبیر کے مالک ہیں۔ ‘‘
’’فتاویٰ شامی‘‘میں بھی اس عبارت کو نقل کیاگیاہے۔
’’علمِ طبیعی‘‘ کےمتعلق ’’رد المحتار‘‘میں ہے:
’’وفي فتاوی ابن حجر: ما کان منہ علی طريق الفلاسفۃ حرام؛ لأنہ يؤدي إلٰی مفاسد کاعتقاد قدم العالم ونحوہٖ وحرمتہ مشابہۃ لحرمۃ التنجيم من حيث إفضاء کل إلی المفسدۃ۔ ‘‘
ترجمہ: ’’علامہ ابن حجرہیتمی ؒ کے فتاویٰ میں ہےکہ: جوعلمِ نجوم فلاسفہ کے طرز پر ہووہ حرام ہے، کیونکہ وہ کئی مفاسد کاباعث ہے، مثلاً: عالم کا قدیم ہونا وغیرہ اور اس کی حرمت بھی علمِ نجوم کی طرح ہے کہ دونوں فسادِ اعتقاد کےباعث ہیں۔ ‘‘
اسی کتاب میں’’ علمِ رمل‘‘ کےحکم کے ضمن میں مرقوم ہے:
’’وفي فتاوی ابن حجر أن تعلمہ وتعليمہ حرام شديد التحريم لما فيہ من إيہام العوام أن فاعلہ يشارک اللہ تعالیٰ في غيبہ۔‘‘
ترجمہ:’’ علامہ ابن حجرہیتمی ؒ کے فتاویٰ میں ہےکہ: علم رمل کاسیکھنا، سکھانابالکل حرام ہے، کیونکہ اس کی بنیاد پرعوام کویہ غلط فہمی لاحق ہوسکتی ہے کہ اس کاکرنے والااللہ تعالیٰ کے ساتھ علمِ غیب کی صفت میں شریک ہے۔ ‘‘
یہاں دو چیزوں کو الگ الگ رکھنا اور سمجھنا ضروری ہے، ایک عصری علوم ہیں اور ایک ان کو حاصل کرنے کا عصری نظامِ تعلیم ہے، دونوں کاحکم الگ الگ ہے:
الف: چنانچہ جن علوم وفنون پر’’عصری علوم ‘‘کا اطلاق کیاجاتاہے، ان میں سے بہت سے مفید علوم فنون بھی ہیں، جن سے اجتماعی زندگی میں بیش بہا فوائد حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں جن کی اُمت کو ضرورت ہے اور فی زمانہ ان میں مہارت حاصل کیے بغیر اُمت کی حفاظت کرنا ہی ناممکن یامشکل ہے۔ بدقسمتی سے بعض ایسی چیزوں کو بھی علم وفن کا درجہ دیا گیا ہے جن کے مقاصد ونتائج شرعی تعلیمات سے متصادم ہیں، اس لیے درج بالا ضابطے کے مطابق ان میں سے بعض علوم کی حیثیت فرضِ کفایہ، بعض کی مندوب ومستحب، جبکہ بعض کی مکروہ ومذموم کی ہے۔
ب:دوسری چیز عصری نظامِ تعلیم ہے، اس کاحکم مختلف ہے۔
اس کی تفصیل یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں عصری علوم کاجو نصاب ونظام رائج ہے، ان دونوں میں بعض سنگین قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں، ان غلطیوں کانتیجہ ہے کہ جو اَفراد اس سےگزرجاتے ہیں، ان پر اس کے برے اثرات اور غلط نتائج مرتب ہوتے ہیں، چنانچہ ہمارا محدود مشاہدہ یہ ہے کہ معاشرےمیں تین قسم کے اَفراد اس نظام سےگزرتے ہیں:
1:ٹھیٹھ دینی اور مذہبی سوچ وخاندان والے افراد، ان میں سے بہت سے افراد اس کے مضر اثرات سے محفوظ ہوجاتے ہیں، لیکن اس طبقے کی بھی ایک خاصی بڑی اور قابلِ لحاظ تعداد ایسے ہی افراد کی ہے جو اس نظام میں رہنے کی وجہ سے متعدد عملی اور نظریاتی کوتاہیوں اور گناہوں کےشکار ہوہی جاتے ہیں۔
2:بےدین اور آزاد خیال قسم کے لوگ، ان کی بے دینی اور آزاد خیالی میں اضافہ ہوجاتاہے، بلکہ اس نظام سے ان کی ایک گونا تائید ہوتی ہے، ان کی بے دینی کے لیے مضبوط سہارا مہیا ہوجاتاہے۔
3: خالی الذہن افراد، ان کی اکثریت اس نظام میں کچھ عرصہ تک رہ کر بگڑ جاتی ہے، متعدد عملی اور نظریاتی منکرات وگمراہیوں کا شکار ہوجاتی ہے۔
گزشتہ عنوان’’منقح ضابطہ‘‘ کے تحت جو تفصیلات ذکر کی گئیں ہیں، ان کی روشنی میں اس پر غور کیا جائے کہ کیا موجودہ نظامِ تعلیم میں رہ کر عصری علوم حاصل کرنا جائز ہے یانہیں؟ تو بات واضح ہوجاتی ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، حضرات فقہائےکرام نے ’’علمِ نجوم‘‘وغیرہ کی ممانعت کی علت یہ ذکر فرمائی ہے کہ یہ اکثر لوگوں کو شرعی کوتاہیوں میں مبتلا کرنےکاباعث ہے، عصری نظامِ تعلیم میں اس سے بڑھ کر یہ خرابی پائی جاتی ہے۔
یاد رہے کہ بعض افراد اگر چہ اس نظام میں رہتے ہوئے بھی شرعی کوتاہیوں اور معاصی سے بچ جاتے ہیں، تاہم فقہی احکام کی تفریع وترتیب میں ہرہرفرد ملحوظ نہیں ہوتا، بلکہ عام طور پر اکثر افراد کالحاظ کیا جاتا ہے، بلکہ حضرات فقہائے کرام کی تمام تر جزئیات کو سامنےرکھ کر غور کیا جائے توتحقیقی بات یہ سامنے آتی ہے کہ :
الف: اگر کوئی چیز خود کسی معصیت کاسبب ہو، لوگوں میں کسی گناہ کا میلان وحرکت پیدا کرنےوالی ہو تو وہ بہرحال ناجائز ہے۔
ب:کوئی چیز اس معنی میں معصیت کا سبب نہ ہو، لیکن بہرحال اس کی وجہ سے لوگ کسی گناہ کے شکار ہوجاتے ہوں، ایسی چیزوں کا شرعی حکم متعین کرنے میں عام افراد یااکثرافراد کالحاظ رکھاجاتاہے۔
حضرات فقہائےکرام کی درج ذیل جزئیات کو سامنے رکھاجائے تو یہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے، ان شاء اللہ! ’’فتاویٰ ہندیہ‘‘میں ہے:
’’والأصل الفاصل بينہما أن ينظر إلی الأصل، فإن کان الأصل في حقہٖ إثبات الحرمۃ وإنما سقطت الحرمۃ لعارض، ينظر إلی العارض إن کان مما تعم بہ البلوی وکانت الضرورۃ قائمۃ في حق العامۃ فہي کراہۃ تنزيہ، وإن لم تبلغ الضرورۃ ہٰذا المبلغ فہي کراہۃ تحريم فصار إلی الأصل، وعلی العکس إن کان الأصل الإباحۃ ينظر إلی العارض، فإن غلب علی الظن وجود المحرم فالکراہۃ للتحريم وإلا فالکراہۃ للتنزيہ۔ ‘‘
ترجمہ:’’ فیصلہ کن ضابطہ یہ ہے کہ:کسی عمل(چیز) کے اصل کو دیکھا جائے :اگرکوئی چیز اصلاً حرام ہو، مگر اس کی حرمت کسی عارض کی وجہ سے ساقط ہوئی ہو تو دیکھا جائے گا: اگرعارض میں عمومِ بلویٰ ہواورعوام الناس کی حد تک ضرورت درپیش ہو، تووہ عمل مکروہِ تنزیہی قرارپائے گا۔ اگرعارض ضرورت کی حد تک نہ پہنچا ہو تو اصل کالحاظ کرکے وہ مکروہِ تحریمی قرار پائے گا۔ اس کے برعکس اگرکوئی چیز اصلاً مباح ہو تو عارض کو دیکھا جائے گا: اگرغالب گمان کے مطابق اس میں حرام کاارتکاب کرناپڑے تووہ مکروہِ تحریمی قرار پائے گا، ورنہ مکروہِ تنزیہی۔ ‘‘
’’درِمختار‘‘ میں ہے:
’’(وذہب وحديد وصفر) ورصاص وزجاج وغيرہا لما مر فإذا ثبت کراہۃ لبسہا للتختم ثبت کراہۃ بيعہا وصيغہا لما فيہ من الإعانۃ علی ما لايجوز وکل ما أدی إلٰی ما لا يجوز لا يجوز، وتمامہ في شرح الوہبانيۃ۔ ‘‘
ترجمہ: ’’سونا، لوہے، پیتل، تانبا، شیشہ وغیرہ کی انگوٹھی کااستعمال (پہننا) چونکہ ممنوع ہے، جب اس کااستعمال ممنوع ہے تواس کافروخت کرنا اوربنانا بھی مکروہ ہے، کیونکہ اس میں ناجائز کام میں تعاون ہے، اورجوچیز بھی ناجائز کام کا ذریعہ بنتی ہے، وہ ناجائز ہے۔ ‘‘
’’بدائع‘‘میں ہے:
’’ولأن الاستمتاع بہا بما يقرب من الفرج سبب الوقوع في الحرام۔ قال رسول اللہ - صلی اللہ علیہ وسلم - ألا إن لکل ملک حمی وإن حمی اللہ محارمہ، فمن حام حول الحمی يوشک أن يقع فيہ وفي روايۃ من رتع حول الحمی يوشک أن يقع فيہ، والمستمتع بالفخذ يحوم حول الحمی ويرتع حولہ، فيوشک أن يقع فيہ دل أن الاستمتاع بہ سبب الوقوع في الحرام وسبب الحرام حرام، أصلہ الخلوۃ بالأجنبيۃ۔‘‘
ترجمہ: ’’شرم گاہ کے آس پاس سے لطف اندوز ہوناحرام جماع کاذریعہ ہے (اس وجہ سے منع ہے)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاارشادِ گرامی ہےکہ:’’ہربادشاہ کی ایک (شاہی) چراگاہ ہوتی ہے (جہاں عوام کو جانے کی اجاز ت نہیں ہوتی اور وہاں داخل ہونا جرم قرار پاتا ہے) اور خدا تعالیٰ کی چراگاہ حرام چیزیں ہیں، جوشخص چراگاہ کے اردگرد گھومے گا تو خطرہ ہے کہ وہ اس میں پڑجائے۔‘‘ دوسری روایت میں ہے کہ:‘‘ ہربادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، جوچراگاہ کے ارد گرد جانور چراتا ہے تو خطرہ ہے کہ اس میں پڑجائے۔‘‘ تو حیض کی حالت میں بیوی کی ران سے لطف اندوز ہونا چراگاہ کے اردگرد گھومناہے تو ممکن ہے کہ شوہر جماع کربیٹھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس جگہ سے لطف اندوز ہونا حرام میں پڑنے کا ذریعہ ہے اور حرام کا ذریعہ بھی حرام ہوتا ہے۔ اس کی دلیل اجنبی عورت کے ساتھ خلوت کا مسئلہ ہے (کہ حرام کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے روایات میں اس سے ممانعت وارد ہے)۔ ‘‘
’’ہدایہ‘‘ میں ہے:
’’و لايقرب المظاہر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر إلی فرجہا بشہوۃ حتی يکفر‘‘؛ لأنہ لما حرم الوطء إلی أن يکفر حرم الدواعي للإفضاء إليہ، لأن الأصل أن سبب الحرام حرام کما في الاعتکاف والإحرام وفي المنکوحۃ إذا وطئت بشبہۃ۔ ‘‘
ترجمہ:’’ کفارہ اداکرنے سے پہلےظہارکرنے والے کوبیوی کے پاس جانا، اسے مس کرنا، بوسہ لینا، شہوت کے ساتھ شرم گاہ کودیکھنا سب باتیں منع ہیں، کیونکہ جب کفارہ سے پہلے وطی حرام ہےتواس کے دواعی بھی حرام ہیں، کیونکہ وہ حرام کےذرائع ہیں۔ ضابطہ یہ ہے کہ: حرام کا ذریعہ بھی حرام ہے، جیساکہ اعتکاف، احرام اور اپنی اُس بیوی کے ساتھ جس کے ساتھ شبہ کی بنیاد پر وطی کی گئی ہو، یہ باتیں ممنوع ہیں۔ ‘‘
درج بالا ضابطے کی روشنی میں مخلوط نظامِ تعلیم کو دیکھاجائے تو صاف طور پر واضح ہوجاتاہے کہ یہ نظام خود معصیت کی طرف میلان وحرکت پیدا کرتاہے۔
شاید یہی وجہ ہے کہ ہماری معلومات کے مطابق اکثر اہلِ فتویٰ علماء کرام اس نظم میں تعلیم حاصل کرنے کی ممانعت کرتے ہیں۔
ہم پہلے وضاحت کےساتھ ذکر کرچکے ہیں کہ عصری علوم اور عصری نظام ونصابِ تعلیم، دو جدا جدا چیزیں ہیں، دونوں کے احکام مختلف ہیں، لہٰذا تعلیم کے نظام ونصاب کی وجہ سے خود عصری علوم کی مذمت وممانعت کسی طرح ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا کرنے کاکام یہ نہیں ہے کہ عصری علوم ہی سے ہاتھ دھو کر بیٹھ جائیں، بلکہ جیسا کہ پہلے ذکر کیاجاچکا ہےکہ ان میں سے بعض علوم فرضِ کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں جن کو اجتماعی سطح پر چھوڑنا شرعی نقطۂ نظر سے درست ہی نہیں ہے۔ کرنےکاکام اگر ہے تو یہ ہے کہ: ہرمسلمان اپنی استطاعت کی حد تک نصاب ونظام کی تبدیلی اور دینی تعلیمات وہدایات کے مطابق اس کی تشکیلِ نومیں اپنا کردار ادا کرے۔ کوئی حکومتی ڈھانچہ میں خود یا بالواسطہ اثر ورسوخ رکھتاہے تو وہ وہاں اس کام کے لیے فکرمندی کےساتھ کام شروع کرے، کوئی اس طرح اثر ورسوخ نہ رکھتا ہو تو وہ اپنی حد تک جو کچھ ہوسکے کرڈالے، جب تک حکومتی لحاظ سے دینی تعلیمات کے مطابق ڈھانچہ تعمیر اور پھر رائج نہ ہو، اس وقت تک کچھ تجربہ کار اور فکر مند ایسے طریقوں سے ان علوم کے پڑھنےپڑھانے کا انتظام کریں جو شرعی تعلیمات سے ہم آہنگ ہوں۔
جس طرح عصری علوم کی تحصیل کو بالکل چھوڑنا اور اس پر اصرار کرنا دانش مندی سےمتصادم اور انتہا پسندی ہے، یوں ہی ناجائز عناصر پر مشتمل نظام میں تعلیم حاصل کرنے پر اصرار کرنا بھی دانش مندی سےمتصادم اور انتہا پسندی ہے۔ پہلی صورت میں اگر ضروری دنیوی تقاضے فوت ہوجاتے ہیں تو دوسری صورت میں دینی احکام سے روگردانی پائی جاتی ہے۔ دینی نفسیات کی کمزوری کا نتیجہ ہے کہ پہلی صورت کی تو مذمت کی جاتی ہے، لیکن دوسری صورت کی یا تو مذمت کرنےسے رُکا جاتاہےاور یا اس کی تائید وتصویب کی جاتی ہے۔
اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُمتِ مرحومہ کی حالت پر خصوصی رحمتیں نازل فرمائیں، اس کو ذلت وپستی کے گڑھےسے نکال کر عزت ورفعت اور خلافت وقیادت کی اہلیت ولیاقت نصیب فرمائیں، تاکہ اس کا چھوٹا بڑا ہر منصوبہ دینی سانچے اور مذہبی قالب کےاندر ہو، واللہ تعالیٰ أعلم بالصواب۔