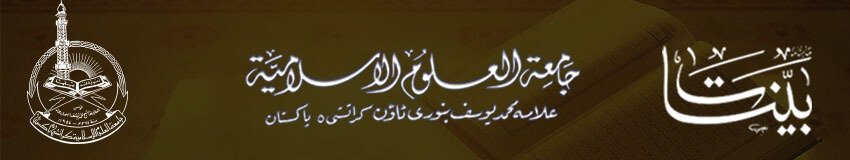
’’مصابیح السنۃ‘‘ متونِ حدیث کی کتابوں میں مشہور ومعروف کتاب ہے، جس کو امام بغوی شافعیؒ (متوفی: ۵۱۶ھ) نے احادیث کی معروف کتابوں سے دین اسلام کے مختلف شعبوں کے متعلق احادیث کا انتخاب کرکے ابواب کی شکل میں مرتب کیا، اختصار کے پہلو کو مدِنظر رکھتے ہوئے سند کو حذف کیا، خال خال ہی کسی مقام پر راوی کا نام ذکر کیا، کتاب میں احادیث کو جامع کتابوں کے طرز پر مرتب کرکے ہر باب کو دو فصلوں میں تقسیم کیا، ایک فصل میں ’’صحاح‘‘ یعنی بخار ی ومسلم کی روایت کردہ احادیث کا ذکر کیا، اور دوسری فصل میں ’’حسان‘‘ یعنی نسائی، ابن ماجہ اور ترمذی وغیرہ کی مرویات کا ذکر کیا۔ صاحبِ مصابیح کی یہ تقسیم ’’صحاح ‘‘اور ’’حسان‘‘ ان کی اپنی اختیار کردہ اصطلاح ہے، جس کو کسی نے عام طور پر محدثین نے تسلیم نہیں کیا، اس لیے کہ جس طرح بخاری ومسلم’’ صحاح‘‘ پر مشتمل ہیں، ایسے ہی حسن احادیث بھی ان میں پائی جاتی ہیں، اور باقی کتابوں کی مرویات کو حسن کا نام دے کر ذکر کیا ہے، باوجود یہ کہ ان میں حسن کے علاوہ صحیح کی بھی وافر مقدار پائی جاتی ہے، لہٰذا صحیح وحسن سے محدثین کے ہاں مشہور اصطلاح مراد نہیں ہے، بلکہ موصوف کی اپنی اختیار کردہ اصطلاح ہے، اور انہوں نے اپنی کتاب کو اسی اصطلاح کے تحت مرتب کیا ہے۔
موصوف کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بےپناہ مقبولیت سے نوازا، محدثینِ عظام نے اس کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، چنانچہ خطیب تبريزیؒ نے استدراک کرکے مزید ايک فصل کے اضافہ کے ساتھ راوی کے نام کا التزام کرتے ہوئے کتابوں کے نام بھی ذکر کیے، کسی نے اس عظیم کتاب کے حواشی لکھے، تو کسی نے روایات کی تخریج کرکے اس کتاب کی خدمت میں حصہ لیا، اسی سلسلہ کی کڑی میں امام وحافظ، فقیہ ومحدث شہاب الدین فضل اللہ بن حسن تورپشتی ؒ (متوفی:۶۶۱ھ) نے اس کتاب کی خدمت میں حصہ لیتے ہوئے ایسی عظیم شرح لکھی جو شارحین حدیث کے لیے ایک مصدرومرجع بن گئی، ذیل میں اس عظیم شارح کی سوانح حیات اور شرح کے بارے میں مختصر تعارف پیش کیا جاتا ہے۔
فضل اللہ نام ہے، شہاب الدین لقب، کنیت ابو عبد اللہ اور تورپشتی تورپشت نامی جگہ کی طرف نسبت ہےجو موصوف کی جائے پیدائش ہے۔ اہلِ تراجم وسیر نے پورا نام ونسب ’’فضل اللہ بن حسن بن حسین بن یوسف تورپشتی‘‘ بیان کیا ہے۔ (۱)
’’تورپشت‘‘ نامی بستی میں موصوف کی ولادت ہوئی، یہ بستی ’’کرمان‘‘ میں ’’یزد‘‘کے جنوب مغربی جانب ۲۵ ؍کلومیٹر پر سنگ مرمر کی کان کے پاس تین چار سو افراد کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، جو زیادہ تر سنگتراش افراد پر مشتمل ہے، (۲) اور ’’شیراز‘‘ کے مضافات میں واقع ہے، چنانچہ علامہ سبکیؒ صاحب (متوفی: ۷۷۱ھ) ’’طبقات الشافعیۃ الکبریٰ‘‘ میں (۸/۳۴۹) رقم طراز ہیں کہ موصوف ’’شیراز‘‘ کے محدث وفقیہ ہیں۔ تاریخِ ولادت کے بارے میں کہیں تاریخی مصادر میں ذکر نہیں ملتا ہے، البتہ ایک دینی گھرانہ میں ان کی ابتدائی تعلیم وتربیت ہوئی، اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے اپنی شرح میں اپنے والد کی سند سے ایک روایت ذکر کی ہے، مزید اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے والد صاحب علم کے ساتھ حدیث میں مقام رکھتے تھے، اس لیے تورپشتی صاحبؒ ان کی سند سے روایت اپنی شرح میں لائے ہیں، ورنہ ہر کس وناکس کی روایت ذکر نہیں کی جاتی ہے۔(۳)
ابتدائی تعلیم کے بعد ’’شیراز‘‘ کے بڑی اہلِ علم شخصیات کے سامنے زانوئے تلمذ تہ کیا، اور مزید علمی تشنگی کو بجھانے کے لیے ’’ہمذان‘‘ شہر کا رخ کیا، جس کی طرف اشارہ موصوف کی ایک روایت سے ملتا ہے، جو انہوں نے اپنی شرح کے مقدمہ (۱/ ۳۱) میں شیخ شہاب الدین عبد الوہاب (جامع مسجد عتیق کے امام) سے ذکر کی ہے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض محدثین سے ’’ہمذان‘‘ میں سنا ہے۔ (۴)
تورپشتی صاحبؒ نے کچھ عرصہ حرمین شریفین میں بھی گزارا ہے، جیسا کہ شرح کے ’’کتاب الصلوات‘‘ کے ’’باب المواقیت‘‘ (۱/۱۸۱) وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے، تو اس میں یہ امکان ہے کہ انہوں نے وہاں کے بڑے شیوخ واساتذہ سے فیض حاصل کیا ہو، اور کئی تشنگانِ علومِ نبوت نے موصوف سے بھی خوشہ چینی کی ہوگی۔
حافظ تورپشتی ؒ کی تبحرِ علمی، علومِ شریعت میں مہارتِ تامہ، حدیث وفقہ میں ملکہ، علمِ کلام وتصوف میں یدِ طولی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ انہوں نے بہت سارے شیوخ سے سیرابی حاصل کی ہوگی، لیکن مصادرِ تاریخ میں بہت ہی گنی چنی شخصیات کا ذکرآتا ہے، جن کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:
۱-والد محترم ابو سعید حسن بن حسین بن یوسف تورپشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے۔
۲-ابو غانم مہذب بن حسین سے ایک روایت ’’کتاب القدر‘‘ (۱/۵۳) میں روایت کی ہے۔
۳-عبد الوہاب بن صالح جامع مسجد عتیق، ہمذان کے امام سے بخاری روایت کی ہے، جس کا تذکرہ موصوف کے مقدمہ سے (۱/ ۳۱) ملتا ہے۔
۴-ابو عبد اللہ محمد بن محمد بن غانمؒ سے ’’کتاب الإیمان‘‘ (۱/ ۵۳) میں ایک روایت بطور اجازت لی ہے۔
۵-شیخ شہاب الدین سہروردی ؒ سے تصوف میں کسبِ فیض کیا۔ (۵)
غالب گمان یہی ہے کہ حافظ تورپشتی صاحبؒ نے تعلیمی مراحل کی تکمیل کے بعد درس وتدریس کا آغاز کیا ہوگا، اگرچہ مصادر ومراجع میں تاریخ وسن کی کوئی تعیین نہیں کہ کب انہوں نے تدریس کی ابتدا کی؟ لیکن مصابیح السنۃ کی شرح ’’شیراز‘‘ کے طلبہ کے اِصرار پر لکھی تھی، جس کی وضاحت خود انہوں نے مقدمہ (۱/۲۹) میں کی ہے، موصوف کی تصریح سے معلوم ہوجاتا ہے کہ انہوں نے تدریسی خدمات کا بڑا سلسلہ شیراز میں انجام دیا، گو کہ عمر کے آخری حصہ میں ’’کرمان‘‘ منتقل ہوگئے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ انہوں نے بڑا عرصہ درس دیا ہوگا کہ طلبہ ان سے واقف ہوئے کہ حافظ تورپشتی ؒ ’’مصابیح السنۃ‘‘ کی مشکلات کی تسہیل کرسکتے ہیں اور وہ اس میدان کے کہنہ مشق آزمودہ تجربہ رکھنے والی شخصیت ہیں، ورنہ واقفیت اور طویل تجربہ کے بغیر طلبہ مطالبہ کیسے کرتے؟!
افسوس ہے کہ طویل عرصہ تدریسی وتالیفی خدمات کے باوجود تاریخ کے اوراق میں بس چیدہ چیدہ تلامذہ کا ذکر دیکھنے کو ملتا ہے، جن کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں:
۱-مجد الدین آپ کے صاحبزادے ہیں، تصوف وتزکیہ میں استفادہ کرکے آپ کے انتقال کے بعد سجادہ نشین بنے۔
۲-شیخ صدر الدین مظفربن محمد عمری عدویؒ، صاحبِ ’’التلویح في شرح المصابیح‘‘ ہیں۔
۳-امیر اصیل الدین عبد اللہ بن علی عدوی محمدی ؒ۔
۴-رشید محمد بن ابی القاسم مقریؒ، جن سے رودانی ؒ نے ’’مصابیح‘‘ کی شرح روایت کی ہے۔ (۶)
حافظ تورپشتی ؒمحقق، مدقق، فقیہ، اصولی، مفسر کے ساتھ تصنیف ومیدان کے صرف شہسوار نہیں تھے، بلکہ سرخیل تھے۔ عربی وفارسی زبان پر اچھی طرح عبور حاصل تھا، دونوں زبانوں میں گرانقدر تالیفی خدمات ہیں، مختصر تعارف کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں:
۱- ’’الأربعین‘‘: جس کا تذکرہ حافظ سخاویؒ (متوفی۹۰۲ھ) نے اپنی کتاب ’’الضوء اللامع‘‘ میں کیا ہے۔ (۷) یہ کتاب جلد ہی شیخ عثمان بن فیروز کی تحقیق سے مکتبہ اسماعیل برطانیہ سے چھپ جائے گی۔
۲-’’مطلب الناسک في علم المناسک‘‘: اس کتاب میں حج کے مسائل کا بیان ہے، جس میں چالیس ابواب مرتب کیے ہیں۔ (۸) اور اس کتاب کا حوالہ شرح میں کئی جگہ دیا ہے، مکتبہ اسماعیل برطانیہ سے سید ابن محمد السناری کی تحقیق سے چھپ گئی ہے۔
۳-’’تحفۃ السالکين‘‘: یہ کتاب فارسی زبان میں ہے، جس میں اعتقادات و معاملات کے ساتھ اخلاق وآداب پر بحث ہے، پھر اس کا اختصار کرکے ’’تحفۃ المرشدین‘‘ کا نام رکھا۔ (۹)
۴- المعتمد فی المعتقد: یہ فارسی زبان میں عقائد پر مشتمل ایک کتاب ہے۔ (۱۰)اردو زبان میں مولانا اختر محمد خان حنفی نے ترجمہ کیا ہے، اور مختلف مکتبات سے ہندو وپاک، ایران میں شائع ہوچکی ہے، عربی زبان میں استاذ محترم مولانا محمد انور بدخشانی ؒ(متوفی۱۴۴۶ھ) نے ترجمہ کیا، جو ابھی تک غیر مطبوع ہے۔
۵- قرآن کریم کی تفسیر : حافظ تورپشتی ؒ نے ’’المیسر شرح مصابیح السنۃ‘‘ (۴/ ۱۳۶۲) کے اختتام میں خاص منہج واُسلوب کے ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کا ارادہ ظاہر کیا ہے، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی اور یہ عظیم کام حسرت ہی رہ گئی۔
اخیر عمر میں ’’شیراز‘‘ سے کرمان آگئے تھے اور یہیں ان کی وفات ہوئی، البتہ سنِ وفات میں اہلِ سیر وطبقات کا اختلاف ہے، لیکن بظاہر درست وہ ہے جو ان کے صاحبزادے عبد ا للہ نے اپنے والد صاحب کے خطی نسخے کے آخر میں ۶۶۱ ہجری کی تاریخ ذکر کی ہے (۱۱)۔ اور اسی تاریخ پر اعتماد ملا علی قاری ؒ (متوفی ۱۰۱۴ ھ) نے ’’طبقات‘‘ (۲/ ۵۴۵) میں، علامہ خیر الدین زرکلی ؒ(متوفی ۱۳۹۶ھ)نے ’’الأعلام ‘‘ میں (۱۲)، مولوی فقیر محمد جہلمیؒ (۱۹۱۶ء) نے ’’حدائق الحنفیۃ ‘‘ میں (۱۳) اور مولانا ڈاکٹر محمد عبدالحلیم چشتی صاحبؒ (متوفی ۱۴۴۲ھ) نے فوائدِ جامعہ (۲۸۷) میں کیا ہے۔
کتاب کا نام اور مصنف کی طرف نسبت: حافظ تورپشتی ؒ کی طرف کتاب کی نسبت میں کوئی تردد نہیں، اس لیے کہ تمام اہلِ سیر وطبقات نے کتاب کی نسبت موصوف کی طرف کی ہے۔ (۱۴) اور مزید برآں یہ کہ شارحینِ حدیث عام طور پر اور ’’مشکاۃ المصابیح‘‘ کے شارحین بالخصوص ان کی طرف نسبت کرتے آرہے ہیں۔
کتاب کے اختتام پر ’’باب ثواب ہٰذہ الأمۃ(۴/ ۱۳۶۲)‘‘ میں نام کی تصریح کی ہے کہ میں نے مذکورہ شرح کا نام (المیسّر) رکھا ہے۔ اسماعیل پاشا بغدادیؒ نے ’’ہدیۃ العارفین‘‘ میں (في شرح المصابیح) کا اضافہ کیا ہے، ابھی اسی نام سے شہرت ہے۔ (۱۵)
المیسّر کی وجہ تالیف: حافظ تورپشتی ؒ نے ’’شیراز‘‘ کے تلامذہ کی خواہش پر ’’مصابیح‘‘ کی شرح کا آغاز کیا، جس کی طرف اشارہ مقدمۂ کتاب میں پایا جاتا ہے، البتہ تاریخ معلوم نہیں کہ شرح کی ابتدا کب ہوئی؟ اور اختتام کی تاریخ کتاب کے آخر سے معلوم ہوتی ہے، چنانچہ موصوف رقم طراز ہیں: ’’وقع الفراغ من إنشاء ہذا الکتاب في آخر جزء من يوم الجمعۃ لسادس من صفر سنۃ ستين وستمائۃ‘‘ (۴/ ۱۳۶۴)یعنی: ’’کتاب کے آخر ی حصہ سے فراغت جمعۃ المبارک کے دن۶ ؍صفر المظفر ۶۶۱ ہجری کو ہوئی۔‘‘
کتاب کے محقق طبعات: ’’المیسر في شرح المصابیح‘‘ کے متعدد خطی نسخے ہیں، سب سے پہلے اس کتاب کی تحقیق عبد الحمید ہنداوی نےکی، اور کتاب کو مخطوط سے مطبوع کی شکل میں مکتبہ نزارمصطفیٰ باز سعودی عرب سے شائع کیا، لیکن اس میں جابجا کچھ کلمات اور جملوں کا سقوط ہےجو بسا اوقات عبارت کے سمجھنے میں خلل کا باعث ہوتاہے، پھر ان کے بعد فہد ابن ابراہیم بن عبد اللہ شمسان نے ایک حصہ پر محمد بن سعود یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے مقالہ میں ’’کتاب الأسامي‘‘ کے ’’باب الآداب‘‘ سے لےکر ’’کتاب الفتن‘‘ کے ’’باب لا تقوم الساعۃ إلا علی الأشرار‘‘ تک تحقیق وتعلیق کی، اس حصہ میں جابجا عبد الحمید ہنداوی کی تحقیق کی فروگزاشتوں کی طرف بھی تنبیہ کی ہے، لیکن چونکہ یہ کام نامکمل تھا، بنا بریں شیخ حامد محلاوی نے پوری کتاب پر تحقیق کی جو قریب ہی میں معروف طباعتی ادارے ’’الأسفار‘‘ سے چھپ رہی ہے، اُمید ہے کہ اس ایڈیشن میں پچھلے طبعات میں واقع تسامحات کا ازالہ کرنے کی کوشش کی ہوگی۔
’’المیسر‘‘ محدثین کی نظر میں: حافظ تورپشتی صاحبؒ کی ایک عمدہ شرح ہے، جس میں حدیث کی شرح مختصر ہے، لیکن بلیغ اور دقیق نکات ولطائف کا ایک گنجینہ ہے، جس سے استفادہ بڑے شارحین حدیث نے کیا ہے، علامہ سبکی ؒ (متوفی۷۷۱ھ) ’’طبقات الشافعیۃ‘‘ (۸/۳۴۹) میں رقم طراز ہیں: ’’حافظ تورپشتی ؒنے مصابیح کی بڑی عمدہ شرح کی ہے۔‘‘
ملا علی قاریؒ (متوفی ۱۰۱۴ ھ) فرماتے ہیں: ’’حافظ تورپشتی ؒ نے مصابیح کی بڑی اچھی شرح کی ہے، جو بڑے فوائد اور دقیق مباحث پر مشتمل ہے، جس کو طیبی ؒ اپنی شرح ’’مشکاۃ المصابیح‘‘ میں نقل کرتے ہیں اورہم نے بھی اپنی شرح ’’المرقاۃ علی المشکاۃ‘‘ میں نقل کی ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ حافظ تورپشتی ؒ ’’مصابیح السنۃ‘‘ کے اولین شارح ہیں۔ (۱۶)
علامہ، مفسرِ قرآن شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی:۱۹۷۴ء) نے ’’مشکاۃ المصابیح‘‘ کی شرح ’’التعلیق الصبیح‘‘ کے مقدمہ میں اس شرح کی تعریف یوں کی ہے: ’’میرا اکثر وبیشتر اعتماد اپنی شرح میں شیخ شہاب الدین فضل اللہ بن حسین حنفی کی ’’شرح مصابیح السنۃ‘‘ پر ہے، بخدا یہ ایک عمدہ شرح اور تصنیف لطیف ہے جو حسین فوائد پر مشتمل ہے، اور عمدہ معانی اس میں پنہاں ہیں، جن کو اس سے پہلے ابن آدم اور نہ جنات کا ہاتھ تک لگا ہے۔‘‘ (۱۷)
محققِ کبیر ڈاکٹرمولانا محمد عبد الحلیم چشتی ؒ(متوفی ۱۴۴۲ھ) اپنی معرکہ آراء کتاب فوائد جامعہ شرح بر ’’عجالہ نافعہ‘‘ میں فقہاء ومحدثین (۲۸۷)کے تذکرہ میں حافظ تورپشتی ؒ کے بارے میں لکھتے ہیں: ’’موصوف کو شرحِ حدیث میں امامت کا درجہ حاصل ہے، ان کی ژرف نگاہی، دقیقہ سنجی، نکتہ آفرینی سب کے نزدیک مسلم ہے۔‘‘
کتاب کا منہج واسلوب: حافظ تورپشتی ؒ نے مقدمہ میں اجمالی طور پر اپنے منہج واسلوب کی طرف اشارے کیے ہیں کہ وہ صرف ’’مصابیح السنۃ‘‘ میں مشکل احادیث کی شرح کریں گے، اور ائمہ کے مذاہب اور دلائل سے بحث نہیں کریں گے، لیکن اگر ایک حدیث کی فہم وتفہیم ائمہ کے مذاہب بیان کیے بغیر حل نہیں ہوسکتی تو پھر اس کو بیان کریں گے، اور ایسے مقامات کے مطالعہ کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مصنف حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے، اسی وجہ سے حافظ ابن حجرؒ (متوفی ۸۵۲ھ) نے قاضی علاء الدین کے حوالہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے حافظ سبکیؒ(متوفی۷۷۱ھ) کے حافظ تورپشتی ؒ کو ’’طبقات الشافعیۃ‘‘ میں ذکر کرنے کی تردید کی ہے، اور قاضی صاحبؒ نے وجہ یہ بیان کی ہے کہ موصوف کی شرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ حنفی المسلک ہیں۔ (۱۸) اسی غلط فہمی کا ازالہ حضرت مولانا ڈاکٹر محمد عبد الحلیم چشتی ؒ (متوفی ۱۴۴۲ھ) نے یوں کیا ہے: ’’علامہ سبکیؒ بھی پوری واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے ’’طبقات الشافعیۃ‘‘ میں ان کا تذکرہ دو چار سطروں سے زیادہ نہ کرسکے، لیکن ’’طبقات الشافعیۃ‘‘ میں ان کا تذکرہ کردینے کی وجہ سے علامہ تورپشتی ؒ کا شمار فقہاء شافعیہ میں ہونے لگا، حالانکہ موصوف وسیع النظر اور دقیقہ سنج حنفی تھے، چنانچہ ان کی کتابیں اس امر کا بیّن ثبوت ہیں۔‘‘ (۱۹)
کتاب کی اہم امتیازی خصوصيات مختصر طور پر درج ذیل ہیں:
1- کتاب میں شرحِ حدیث پر مطلق توجہ مرکوز کی گئی ہے، باقی ائمہ کے اختلافات ودلائل سے بحث نہیں کی گئی، اگر کہیں شرحِ حدیث کے ضمن میں ائمہ کے مذاہب کے بیان کی ضرورت محسوس کی گئی تو وہاں پر بیان کیا۔
2-احادیث کی شرح: قرآنی آیات، احادیثِ مبارکہ اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے اقوالِ مبارکہ کی روشنی میں حل کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، جو واضح طور پر جابجا نظر آتا ہے۔
3- اگر کہیں بظاہر آیت اور حدیث میں یا مختلف روایات میں تعارض کی صورت پیش آسکتی تھی، تو اس کے ازالہ کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔
4-اگر حدیث میں کوئی مبہم نام ہے یا راویوں میں کوئی ابہام ہو تو اس کی تعیین بھی کرتے ہیں۔
5-’’مصابیح السنۃ‘‘ کے مختلف نسخوں کی طرف اشارہ کرنے کے ساتھ بعض نسخوں میں غلطیوں کی نشاندہی کرکے صحیح کو واضح فرماتے ہیں۔
6-اگر کسی حدیث میں بظاہر فرقِ باطلہ کی تائید ہوتی ہے یا اس سے وہ لوگ اپنے باطل موقف پر استدلال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں اُصولِ مسلمہ سے ان کے استدلال کو توڑتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے حافظ تورپشتی ؒ سے شرحِ حدیث کا خوب کام لیا ہے، اور ان کے نام کو شارحینِ حدیث کے ناموں میں زندہ رکھا ہے، جس سے اُمید تام ہے کہ ان شاء اللہ اس جہاں میں بھی ان کے ساتھ اصحابِ حدیث کا معاملہ فرماتے ہوئے بلند درجات عطا فرمائیں گے، اللہ ہمیں بھی دین متین کی خدمت، خصوصاً خدماتِ حدیث بہرہ ور فرمائیں اور حدیث کو ہمارے لیے حرز جان بنائیں۔ وصلی اللہ وسلم علی خير خلقہٖ محمد وآلہٖ وصحبہٖ أجمعين۔
۱- ملاحظہ فرمائیں: السبکي، تاج الدین أبو نصر عبد الوہاب ابن تقي الدین (المتوفی:۷۷۱ھ)، طبقات الشافعيۃ الکبری، تحقیق: محمود محمد طناجي، عبد الفتاح محمد حلو، الناشر: ہجر للطباعۃ والنشر والتوزيع (۸/۳۴۹)
حاجی خليفۃ، کاتب چلپی، کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون، الطبعۃ: دار إحیاء التراث العربي (۱/۳۷۳)
النعماني، الجشتي، محمد عبد الحلیم (المتوفی:۱۴۴۲ھ)، الفوائد الجامعۃ شرح برعجالۃ نافعۃ، ناشر: مکتبۃ الکوثر، طبع سوم: ۱۴۳۳ (۲۸۷)
۲- النعماني، محمد عبد الحليم (المتوفی: ۱۴۴۲ھ) الفوائد الجامعۃ شرح برعجالۃ نافعۃ (۲۸۷)
۳-توربشتي، شہاب الدین، فضل اللہ بن حسن بن حسین بن یوسف (المتوفی:۶۶۱ھ)، المیسر في شرح مصابیح السنۃ، تحقیق: عبد الحمید ہنداوي، ناشر: مکتبۃ نزار مصطفی المکۃ المکرمۃ، طبع دوم: ۲۰۰۸ء (۱/۱۱۲)
۴- توربشتي، المیسر في شرح مصابیح السنۃ، تحقیق: فہد بن إبراہيم (۳۷)
۵-النعماني، الجشتي، محمد عبد الحلیم (المتوفی:۱۴۴۲ھ) البضاعۃ المزجاۃ لمن یطالع المرقاۃ، تحقیق: تسلیم الدین، طبع: دار الکتب العلميۃ : ۲۰۱۸ء (۳۹)
۶-مرجع سابق: (۱۲۱)
۷- سخاوي، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمٰن بن محمد بن أبي بکر بن عثمان بن محمد (ت: ۹۰۲ھ) الضوء اللامع لأہل القرن التاسع، ناشر: دار مکتبۃ الحياۃ ، بيروت (۳/ ۱۴۰)
۸- کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون (۲/۱۷۱۹)
۹-مرجع سابق:(۱/ ۳۷۳) ۱۰-مرجع سابق: (۲/ ۱۷۳۳)
۱۱- توربشتي، شہاب الدین، فضل اللہ بن حسن (۶۶۱ھ) المیسر في شرح مصابیح السنۃ، تحقیق: فہد بن إبراہيم بن عبد اللہ الشمسان، ناشر: جامعۃ الإمام محمد بن سعود الإسلاميۃ، ۲۰۰۵ء (ص:۵۱)۔
۱۲- الزرکلي، دمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، (ت: ۱۳۹۶ ھ) الأعلام، ناشر: دار العلم للملايين (۵/ ۱۵۲)
۱۳-جہلمی، فقير محمد (المتوفی ۱۹۱۶م)، حدائق الحنفيۃ، ناشر: مکتبۃ ربيعۃ (۲۳۵)
۱۴-ملاحظہ فرمائیں: سبکي، تاج الدین أبو نصر عبد الوہاب ابن تقي الدین، (المتوفی۷۷۱ھ) طبقات الشافعيۃ الکبری (۸/۳۴۹)،
حاجی خلیفۃ، کاتب چلپی، کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون، (۱/۳۷۳)،
طاشْکُبْري زَادَہْ، أحمد بن مصطفی بن خليل، أبو الخير، عصام الدين (ت ۹۶۸ہـ)، مفتاح السعادۃ ومصباح السيادۃ في موضوعات العلوم (۲/۱۳۰)،
القاري، علي بن سلطان (ت:۱۰۱۴ہـ) الأثمار الجنيۃ في أسماء الحنفيۃ، تحقیق: عبد المحسن عبد اللہ أحمد، ناشر: مرکز البحوث والدراسات الإسلاميۃ بـ ’’ديوان الوقف السني‘‘ - العراق، الطبعۃ: الأولٰی، ۱۴۳۰ہـ - ۲۰۰۹ ء ، (۱/۱۰۴- ۱۰۵)
۱۵- البغدادي، إسماعيل باشا (ت:۱۳۹۹ ہـ)، ہديۃ العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، طبع: دار إحياء التراث العربي، بيروت (۱/ ۸۲۱)
۱۶- القاري، علي بن سلطان (ت ۱۰۱۴ ہـ) الأثمار الجنيۃ في أسماء الحنفيۃ (۱/۱۰۴- ۱۰۵)
۱۷-الکاندہلوي، محمد إدريس (المتوفی:۱۹۷۴ء)، التعلیق الصبیح، الناشر: المکتبۃ العثمانيۃ لاہور، (۱/۵)
۱۸- ابن حجر، أبو الفضل، عسقلاني، أحمد بن علي محمد أحمد بن حجر (۸۵۲ھ) تحقيق: محمد إبراہيم حفيظ الرحمٰن، ناشر: الدار السلفيۃ (۶۱)
۱۹- فوائدِ جامعہ شرح بر عجالہ نافعہ (۲۸۸)